
 پسندیدہ کتابوں میں شامل کریں
پسندیدہ کتابوں میں شامل کریں
فہرست مضامین
- ادبی تنقید کے لسانی مضمرات
- ادبی تنقید کے لسانی مضمرات
- فراقؔ گورکھپوری کی سنگھار رس کی شاعری
- ڈاکٹر فرمان فتح پوری اور نگارِ پاکستان
- شبلی کا تصورِ لفظ و معنیٰ
- غالبؔ – ؔ ایک سادہ بیان شاعر
- پنڈت آنند نرائن ملا کے نثری افکار
- رشید احمد صدیقی کی آخری تحریر ’’عزیزان علی گڑھ‘‘
- فیضؔ کی نظم’ تنہائی‘
- تا نیثیت
- معاصر تنقیدی رویّے اور ناصر عباس نیّر
- مابعد جدیدیت کا نیا چیلنج اور وہاب اشرفی
- اسلوبیاتی نظریۂ تنقید اور مغنی تبسم
- ساختیاتی وپس ساختیاتی فکریات اور گوپی چند نارنگ
- دِوّیہ بانی – ایک دلت بیانیہ
ادبی تنقید کے لسانی مضمرات
پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ
(اصل کتاب سے دو مضامین الگ سے برقی کتب کی صورت میں شائع کئے جا رہے ہیں)
ادبی تنقید کے لسانی مضمرات
یہ امر محتاجِ دلیل نہیں کہ کسی زبان میں ’تنقید‘ اس وقت معرضِ وجود میں آتی ہے جب اس زبان میں ادب کا فروغ عمل میں آ چکا ہوتا ہے۔ ادب کی تخلیق کے لیے اس کے خالق یعنی مصنف (Author) کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مصنف، تخلیق اور تنقید یہ تینوں مل کر ایک مثلث بناتے ہیں۔ مصنف اور تخلیق کے درمیان رشتہ پہلے استوار ہوتا ہے، اور تخلیق کا تنقید (یا نقاد) کے ساتھ رشتہ بعد میں قائم ہوتا ہے۔ تخلیق کلیۃً مصنف کے تابع ہوتی ہے، یعنی کہ جیسا اور جس خیال، نظریے یا طرزِ فکر کا مصنف ہو گا ویسی ہی اس کی تخلیق ہو گی۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ادب اپنے سماج کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ ایک قدیم تصور ہے، اور یہ بات اس لیے درست نہیں کہ سماج خواہ کیسا بھی ہو، ادب ویسا ہی ہو گا جیسا کہ اس کے مصنف کی منشا ہو گی۔ بہت سی باتیں جو سماج میں کہیں نظر نہیں آتیں ، لیکن ادب میں ان کا وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں جو سماج کا حصہ ہیں ، ادب میں ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ادب سماج کا آئینہ ہوتا ہے یا سماج کے تابع ہوتا ہے، درست نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مصنف بھی جو سماج کا ایک فرد ہوتا ہے، سماج کے تابع (یا پورے طور پر تابع) نہیں ہوتا۔ وہ کبھی کبھی سماج سے بغاوت بھی کر بیٹھتا ہے، اس کے بنائے ہوئے اصولوں اور قاعدوں کی نفی بھی کرتا ہے، اور اس کے بندھنوں اور پابندیوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کیوں کہ اس کی اپنی آئیڈیا لوجی ہوتی ہے جواس کی رہبری کرتی ہے۔ سیاست، اور اخلاقیات (جس کا مذہب سے گہرا تعلق ہے)، دونوں سماجی ادارے ہیں اور ہر سماج کسی نہ کسی طور پر سیاسی/ مذہبی / اخلاقی بندھنوں میں جکڑا ہوتا ہے۔ مصنف کی آزادانہ روش یا اس کی باغیانہ فکر یا آئیڈیالوجی سماجی اداروں کے نظریات اور ان کے زریں اصولوں کو صد فی صد تسلیم کرنے کی پابند نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سیاسی وجوہ کی بنا پر پریم چند کے افسانوی مجموعے ’سوزِ وطن‘(۱) کی، اور اخلاقی وجوہ کی بنا پر ایک دوسرے افسانوی مجموعے ’انگارے‘(۲) کی ضبطی عمل میں آئی تھی۔
کسی مصنف کا اپنی تخلیق کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر سچ پوچھا جائے تو ادب سماج کا نہیں ، بلکہ اس کے خالق یعنی مصنف کے ذہن کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہ اس کے خیال، فکر اور آئیڈیا لوجی کی عکاسی کرتا ہے۔ مصنف اپنی تخلیق سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، تنقید یا نقاد سے وہ اتنا ہی دور رہتا ہے۔ مصنف کا تنقید سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن تنقید (بہ لفظِ دیگر نقاد) کا رشتہ تخلیق سے بھی ہوتا ہے اور اس کے خالق (مصنف) سے بھی۔ مصنف، تخلیق اور تنقید (نقاد) کے مابین رشتہ ایک مثلث کی شکل اختیار کر لیتا ہے:
اس مثلث پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ مصنف کا براہِ راست تعلق تخلیق سے تو ہے، لیکن تنقید یا نقاد سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ؛ لیکن نقاد کا رشتہ تخلیق سے بھی ہے اور مصنف سے بھی۔ نقاد اور مصنف کے درمیان رشتے کی نوعیت یک طرفہ ہے، جب کہ تخلیق اور تنقید (نقاد) کے درمیان رشتہ دو طرفہ ہے۔ نقاد اور مصنف کے اس روایتی رشتے پرنہ صرف روسی ہیئت پسندوں نے کاری ضرب لگائی، بلکہ عملی تنقید، نئی تنقید، نئی امریکی تنقید، ساختیاتی وپس ساختیاتی تنقید اور اسلوبیاتی تنقید کے ماہرین نے بھی مصنف کے وجود کی نفی کرتے ہوئے صرف تخلیق یا فن پارے کو خود مکتفی مان کر اپنے تنقیدی فرائض انجام دیے۔ روایتی ادبی تنقید کی روسے تخلیق نقاد کو متاثر کرتی ہے اور نقاد اسی تاثر کو قاری تک پہنچاتا ہے۔ یہ تاثر کئی نقادوں کے درمیان مختلف بھی ہوسکتا ہے، جب کہ تخلیق وہی رہتی ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ مسلّم ہے کہ نقاد جس طرح چاہتا ہے تخلیق کی تشریح (Interpretation) کرتا ہے۔ اِس میں اس کی اپنی پسندیا ناپسند کو حد درجہ دخل ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنقیدی عمل کے دوران اس کے اپنے نظریات، عقائد اور آئیڈیا لوجی حاوی رہتی ہے۔
ادب اور سماج کے تعلق سے یہ بات ملحوظِ خاطر رہنی چاہیے کہ ادب سماج کی رپورٹنگ نہیں۔ یہ کام یا تو صحافت کا ہے یا تاریخ کا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ادب کا مطالعہ ہر گز اس خیال سے نہ کرنا چاہیے کہ اس سے ہمیں معلومات حاصل ہوں گی یا ہمارے علم میں کسی قسم کا اضافہ ہو گا۔ ادب کا مقصد نہ تو رپورٹنگ ہے اور نہ اطلاع رسانی، اور نہ ہی کسی ادیب پر یہ ذمہ داری یا پابندی عائد ہوتی ہے کہ سماج میں اچھا یا برا جو کچھ بھی واقع ہو رہا ہے اس کی وہ رپورٹنگ کرے یا علم کا خزانہ ہمارے سامنے پیش کرے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ادب (یا ادبی متن) میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اسے ادب یا متن سے باہر Verify نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ ادبی متن میں جو کچھ کہا گیا یا بیان کیا گیا ہے وہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے، کیوں کہ متن اور حقیقی دنیا (Text and reality) میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ صحافت اور تاریخ حقیقی دنیا یا Realityسے جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں ، ادب اس سے اتنا ہی دور ہوتا ہے، کیوں کہ ادب فسانہ ہے، حقیقت نہیں (Literature is fiction, not fact)۔ اسی لیے ادب میں ترسیلی وزن (Communicative load) بہت کم ہوتا ہے۔
جب ادب اور سماج کے درمیان رشتے کی نوعیت کا پتا چل گیا تو یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں کہ تنقید کا منصب کیا ہے۔ تنقید کا منصب و مقصد ادب میں سماج کو ٹٹولنا نہیں ، بلکہ اس جمالیاتی حظ اور سرخوشی (Aesthetic pleasure) کو بیان کرنا ہے جو کسی ادبی فن پارے کو پڑھنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ کسی ادبی فن پارے یا کسی نظم کو پڑھنے کے بعد قاری ایک نوع کے جمالیاتی تجربے (Aesthetic experience) سے گزرتا ہے۔ اس تجربے کا بیان ہی ’تنقید‘ ہے۔ یہ بات محتاجِ دلیل نہیں کہ ادب جمالیات کی ایک شاخ ہے۔ بعض ثقہ نقاد یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنقید کا مقصد کسی ادبی فن پارے کو اچھا یا برا بتانا یا اس کی خوبی و خامی کا پتا لگا نا ہے۔ لیکن یہ سائنٹفک یا معروضی نظریۂ تنقید نہیں ، کیوں کہ ایک نقاد جس فن پارے کو اچھا بتاتا ہے، دوسرا نقاد اسی فن پارے کو برا ثابت کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں قاری شش و پنج میں پڑ جاتا ہے اور اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ کس نقاد کی بات مانے -ایسی تنقید داخلی اور تاثراتی تنقید کے زمرے میں آتی ہے۔ ہم عصر ادبی تنقید اب بہت آگے نکل چکی ہے۔ یہ تنقید اب فن پارے کو حسن و قبح یا خوب و زشت کے پیمانے سے نہیں ناپتی، بلکہ اس کا مقصود کچھ اور ہے جس کا ذکر آئندہ سطور میں آئے گا۔
(۲)
یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ادب کی حیثیت ایک فن پارے کی ہے جس کا ذریعۂ اظہار زبان ہے، لہٰذا کوئی بھی ادبی اسکالر یا نقاد شعرو ادب میں زبان کے تفاعل (Interaction)یا اس کے ادبی و شعری وظائف (Functions) سے صرفِ نظر نہیں کر سکتا۔ ادب بالخصوص شاعری میں زبان کا تخلیقی استعمال، جو زبان کے عام استعمال سے مختلف ہوتا ہے، اپنی منتہا کو پہنچ جاتا ہے اور جمالیات کی حدوں کو چھو لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعری میں ترسیلی عمل کا جمالیاتی ترسیلی فنکشن (Aesthetic communicative function) سب سے غالب نظر آتا ہے۔ روایتی موضوعی ادبی تنقید مزاجاً داخلی (Subjective) اور تاثراتی (Impressionistic) تو تھی ہی، اس میں وجدان (Intuition) کی بھی عمل آرائی تھی۔ اس تنقید کی سب سے بڑی خامی (جسے بعض نقاد خوبی سمجھتے ہیں ) یہ تھی کہ یہ مصنف کی بیساکھی کے بغیر دو قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ ایسی تنقید کا دارو مدار مصنف کی شخصیت، اس کے احوال و کوائف (ولادت تا وفات )، نیز اس کے عہد اور اس عہد کے سماجی، سیاسی اور تہذیبی حالات و واقعات اور انقلابات کے ذکر اور تاریخی تناظر پر ہوتا تھا۔ ایسی تنقید میں تخلیق یا فن پارے کو یا اس کے ذریعۂ اظہار کو بالکل پسِ پشت ڈال دیا جاتا تھا، کیوں کہ ادبی نقاد کی تمام تر توجہ خارجی عوامل اور مصنف کے سوانحی حالات ہی پر مرکوز ہو کر رہ جاتی تھی۔ ایسی تنقید کو مصنف اساس یا مصنف مرکز (Author centred) تنقید یا سوا سخی تنقید کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ بیسویں صدی کی آمد آمد تھی کہ مغرب میں ایسی تنقید کا دم خم جاتا رہا۔ جلد ہی مصنف کی موت (’’The death of the author‘‘) کا اعلان بھی ہو گیا۔ (۳)
ہوا یوں کہ بیسویں صدی کے آغاز سے یورپ میں فرڈی نینڈ ڈی سسیور(م ۱۹۱۳ء) کے تازہ لسانی افکار منظرِ عام پر آنا شروع ہو گئے جن سے جدید لسانیات یا دوسرے لفظوں میں ساختیاتی لسانیات (Structural Linguistics) کی داغ بیل پڑی اور اس کی شہرۂ آفاق کتاب Course in General Linguistics کی ۱۹۱۶ء میں اشاعت سے اگر ایک طرف، زبانوں کے تاریخی مطالعے کے علی الرغم، ان کے توضیحی مطالعے اور تجزیے کی راہیں ہموار ہوئیں تو دوسری جانب ساختیات (Structuralism) کے بنیادی تصورات مرتب ہوئے۔ ساختیاتی ادبی تھیوری (Structuralist Literary Theory) کا ماخذ اور نقطۂ آغاز بھی یہی کتاب ہے۔ زبان کے بارے میں سسیور کے تصورات یا اس کے فلسفۂ لسان کے ادب پر اطلاق سے ادبی تنقید کے لسانی مضمرات کا پتا بہ خوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ادب جس کی حیثیت ایک متن (Text) یا کلامیہ (Discourse) کی ہے زبان کے ہی سانچے یا ڈھانچے میں متشکل ہوتا ہے۔ برایں بنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادب فی الحقیقت ’زبان ‘ہے جس کے مضمرات ادبی تنقید کے ہر نئے ماڈل میں دیکھے جا سکتے ہیں۔
(۳)
فرڈی نینڈ ڈی سسیور(لسانیاتِ جدید کا ابوار لآبا) زبان کو ’نشانات کا نظام‘ (System of signs) قرار دیتا ہے اور لفظ کو ’نشان ‘ (Sign) کہتا ہے جو اس کے نزدیک دو رخا ہوتا ہے۔ اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ ہر نشان کی دو ’طرفیں ‘ (Sides) ہوتی ہیں ؛ اس کی ایک ’طرف ‘ (Side) کو ’تصور‘ (Concept) اور دوسری طرف کو ’صوت امیج‘ (Sound-image) کہتے ہیں۔ نشان میں پائے جانے والے اس دوہرے رشتے یعنی ’تصور‘ اور ’صوت امیج‘ کو وہ علی الترتیب signifiedاور signifierبتاتا ہے۔ اردو میں ان کے لیے ’معنی‘ اور ’معنی نما‘ کی اصطلاحیں مستعمل رہی ہیں۔ انھی دونوں سے مل کر ’نشان ‘ بنتا ہے اور اس کے درمیان رشتہ، ’ساختیاتی رشتہ ‘ کہلاتا ہے:
نشان
(Sign)
تصور صوت امیج
((Concept/signified (Sound-image/signifier)
=معنی =معنی نما
سسیور کے تصورِ نشان ہی سے مربوط اس کے ’langue‘ اور ’parole‘ کے تصورات ہیں۔ اس نے ان دونوں میں فرق بتایا ہے۔ اول الذکر اصطلاح ’لانگ‘ اس نے بہ حیثیتِ مجموعی ’زبان‘ کے لیے استعمال کی ہے جو ایک جامع نظام ہے اور جس کی حیثیت تجریدی (Abstract) ہے جس کے اپنے ضابطے اور قاعدے (Rules)ہیں اور اپنی روایات (Conventions) ہیں ، اور جو سماجی اور اجتماعی سروکار رکھتی ہے۔ یہ زبان کے شخصی یا انفرادی اظہار سے ماورا ہے۔ سسیور کی دوسری اصطلاح ’پرول ‘ سے مراد، بہ وقتِ تکلم، کسی فردِ واحد کے ذریعے زبان کا فی الحقیقت استعمال ہے۔ ’پرول‘ درحقیقت ’لانگ‘ ہی سے برآمد ہوتا ہے۔ اگر لانگ پہلے سے موجود نہ ہو تو پرول معرضِ وجود میں نہیں آسکتا۔ اس کی حیثیت انفرادی ہے۔ اسے زبان کا شخصی اظہار بھی کہہ سکتے ہیں۔
لانگ اور پرول کے درمیان اس فرق کے مضمرات کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم ’معنی‘ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سسیور کے خیال کے مطابق کسی نشان (یا دور لفظ) کے معنی کا انحصار رشتوں کے نظام (System of relations) پر ہوتا ہے اور الفاظ رشتوں کے نظام کا حصہ ہوتے ہیں ، لہٰذا معنی کے تعین کے لیے رشتوں کے نظام کا ادراک ضروری ہے۔ اس کے بغیر معنی کا تعین ممکن نہیں۔ سسیور کا یہ بھی خیال ہے کہ نشان بہ ذاتِ خود با معنی نہیں ہوتا، بلکہ نظام میں موجود دوسرے نشانات کی نسبت سے اس میں معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ نسبت تضادو تفریق (Opposition and Contrast) کی ہے، چنانچہ رشتوں کے نظام میں پائے جانے والے تضادات ہی اخذِ معنی میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نشان کا دوسرے نشان کے ساتھ یا ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ جو تفریقی رشتہ ہوتا ہے وہی تعینِ معنی میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔
معنی سے قطع نظر سسیور نے زبان کے تاریخی (Diachronic) اور توضیحی یا یک زمانی (Synchronic) مطالعے کے فرق کو بھی واضح کیا ہے، نیز الفاظ کے عمودی (Paradigmatic) اور افقی (Syntagmatic) رشتوں کے درمیان پائے جانے والے امتیازات کی بھی وضاحت کی ہے۔ (۴)
زبان سے متعلق فرڈی نینڈڈی سسیور کے انھی فلسفیانہ تصورات سے ’ساختیات‘ کی بنیاد پڑی اور ساختیاتی تنقید کو فروغ حاصل ہوا۔ بعدازاں ’پس ساختیات‘ (Post-structuralism)، ’ردِ تشکیل‘ (Deconstruction) اور ’متن و متونیت‘ (Text and Textuality) جیسے تصورات عام ہوئے۔ پس ساختیاتی نظریے کے فروغ کے ساتھ ہی ’قاری اساس تھیوری ‘ (Reader-response Theory) کا وجود عمل میں آیا۔ ان تمام نظریات نے، جن کا تعلق سسیور کے فلسفۂ لسان سے ہے، ادبی تنقید کی کایا ہی پلٹ دی۔
(۴)
جس زمانے میں یورپ میں فرڈی نینڈ ڈی سسیور کے لسانی تصورات عام ہونا شروع ہوئے، تقریباً اسی زمانے میں سوویت یونین میں ماسکو لسانیاتی حلقہ (Moscow Linguistic Circle) کا قیام عمل میں آیا جس کے تحت روسی ہیئت پسندی (Russian Fornalism) پندرہ سال تک (۱۹۱۵تا ۱۹۳۰ء) پھلتی پھولتی اور فروغ پاتی رہی۔ اس لسانیاتی حلقے کے ارکان اپنی تمام ترتوجہ ’ادب کی زبان‘ کے مسائل پر مرکوز کیے ہوئے تھے اور ’ادب کی سائنس‘ کی تشکیل میں مصروف تھے۔ ’ادبیت ‘ کے مسئلے پر بھی انھوں نے غور و خوض سے کام لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ادب میں ادبیت زبان کے مخصوص استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ روسی ہیئت پسند فن پارے کو خود کفیل و خود مختار مان کر اس کے معروضی، تجزیاتی اور سائنسی مطالعے کے حق میں تھے۔ اس کے لیے انھوں نے متن کی سائنسی تفتیش و تجزیے کا ایسا طریقہ اختیار کیا تھا جو شعری زبان کے انوکھے پن کو پوری طرح اجاگر کر دے۔ (۵)
سوویت یونین میں سیاسی پالیسی کی تبدیلیوں کے نتیجے میں ماسکو لنگوِ سٹک سرکل کے بعض ارکان پراگ (چیکوسلو واکیہ) منتقل ہو گئے تھے اور وہاں لسانیات کے ایک دوسرے دبستان پراگ لنگوِ سٹک سرکل (Prague Linguistic Circle) کی بنیاد ڈالی تھی۔ رومن جیکب سن جو ایک مشہور روسی ہیئت پسند تھا دبستانِ پراگ (Prague School) کا ایک ممتاز ماہرِ لسانیات تسلیم کیا گیا ہے۔ پراگ اسکول میں اگرچہ زبان کے کئی نئے نظریات کو فروغ حاصل ہوا، لیکن جیکب سن کی فنکشنل اسٹائل کی تھیوری (The theory of functional style) اس اسکول کا غالباً سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ جیکب سن نے ترسیلی عمل (Act of Communicaton) کے چھے اساسی فنکشنز (Basic Functions) بتائے ہیں :
۱- اطلاعی (Informative)،
۲- جذباتی/محسوساتی (Emotive)،
۳- شعری (Poetic)،
۴- ہدایتی (Directive)،
۵- لسانی (Metalingual)، اور
۶- ارتباطی (Phatic)،
جیکب سن کا خیال ہے کہ ترسیلی عمل کے دوران کئی فنکشنز باہم دگر برسرِ کار رہتے ہیں ؛ ان میں سے کوئی ایک فنکشن غالب رول ادا کرتا ہے جس سے مقصد برآری کا پورے طور پر کام لیا جاتا ہے۔ ادب جو ایک فنی و تخلیقی اظہار ہے؛ اس کی حیثیت جمالیاتی ترسیل (Aesthetic Communication) کی ہے جو ادبی ترسیل ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس ترسیلی عمل کے دوران جذباتی (محسو ساتی )اور شعری فنکشنز غالب رہتے ہیں جہاں زبان کا جمالیاتی و تخلیقی استعمال آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے۔
ادبی یا جمالیاتی اظہار میں زبان کے تفاعل پر رومن جیکب سن کے خیالات نے آگے چل کر اسلوبیات کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جیکب سن کو اہلِ فکر و نظرنہ صرف اس کی ہیئت پسندی اور اسلوبیاتی بصیرت کی وجہ سے یاد رکھیں گے، بلکہ ساختیاتی شعریات کے بنیاد گزار کی حیثیت سے بھی اس کا نام لیا جاتا رہے گا۔
(۵)
اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب کا ذریعۂ اظہار زبان ہے، لیکن یہ روز مرہ کی یاعام بول چال کی زبان نہیں۔ ادب میں زبان کا مخصوص استعمال ہوتا ہے جس سے ادب کی زبان عام بول چال کی زبان سے مختلف ہو جاتی ہے۔ یہی ادبی زبان کہلاتی ہے۔ تخلیقی زبان، ادبی زبان ہی کا دوسرا نام ہے۔ جو خصوصیات تخلیقی زبان میں پائی جاتی ہیں وہ ادبی زبان کا بھی حصہ ہیں۔ زبان کو ادبی یا تخلیقی طور پر برتنے کے لیے یا اسے خصوصی زبان (Language plus) بنانے کے لیے ادبی فن کار مختلف ذرائعِ اظہار (Expressive devices) اختیار کرتا ہے۔ وہ زبان میں تصرف سے کام لیتا ہے، نئے نئے لسانی سانچے تشکیل دیتا ہے اور لسانی ’نارم‘ (Norm) یعنی معمول سے انحراف بھی کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں عام زبان کو ایک نئی اور انوکھی شکل دے دیتی ہیں جس سے یہ زبان ادبی یا تخلیقی اظہار کے لیے موزوں ترین زبان بن جاتی ہے۔
روسی ہیئت پسندوں اور پراگ اسکول کے ماہرینِ لسانیات نے زبان کے خصوصی استعمال پر کافی غور و فکر سے کام لیا ہے اور اسے ادب کی ’ادبیت‘ کی شرط قرار دیا ہے۔ مکارووسکی نے، جو پراگ اسکول کا ایک ممتاز ماہرِ لسانیات اور نقاد تھا، زبان کے مخصوص استعمال سے متعلق ’فورگراؤ نڈنگ‘(Foregrounding) کا نظر یہ پیش کیا۔
یہ نظریہ اس خیال پر مبنی ہے کہ عام زبان اپنے معمول کے مطابق کام کرتی ہے اور بنی بنائی ڈگر پر گام زن رہتی ہے۔ یہ لاشعوری یا خود کارانہ طور پر (Automatically) برتی اور بروئے عمل لائی جاتی ہے، لیکن جب ایک ادبی فن کار اسے اپنے ادبی و تخلیقی اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ بالارادہ اور شعوری کوششوں کے ذریعے اس میں جدت پیدا کرتا ہے، تازگی لاتا ہے اور طرح طرح کے تصرفات سے کام لیتا ہے جس سے زبان کا Automatization ختم ہو جاتا ہے اور یہ زبان اپنی ڈگر سے ہٹ جاتی ہے اور اس میں ندرت اور انوکھا پن پیدا ہو جاتا ہے جو قاری کی توجہ اپنی جانب کھینچتا ہے۔ ادبی زبان بالخصوص شعری زبان کی اسی خصوصیت کو مکارووسکی نے Automatization کے علی الرغم Deautomatizationسے تعبیر کیا ہے۔ وہ پر زور الفاظ میں کہتا ہے:
"The language of poetry must be deautomatized”.
مکارووسکی نے زبان کے اسی Deautomatizationکے لیے ’فور گراؤنڈنگ‘ (Foregrounding) کی اصطلاح استعمال کی ہے، کیوں کہ یہ زبان اپنے پس منظر (Background) سے پیش منظر (Foreground) کی جانب سفر گرنی ہے، اور سامنے یا پیش پیش ہونے کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ شعری زبان میں فورگراؤ نڈنگ اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے جہاں معمول کے مطابق کام کرنے والی یا بنی بنائی ڈگر پر چلنے والی زبان پس منظر میں چلی جاتی ہے اور اس کے برعکس ندرت، جدت اور انوکھا پن رکھنے والی، نیز اپنے معمول یا ’نارم‘ (Norm) سے ہٹی ہوئی زبان سامنے یا پیش منظر میں آ جاتی ہے جو Foregroundedزبان کہلاتی ہے۔ (۶) یہ زبان غیر معمولی اظہاری عمل (Uncommon act of expression) کا نتیجہ ہوتی ہے اور ترسیل کو پیچھے یعنی بیک گراؤنڈ میں دھکیل کر خود سامنے آ جاتی ہے اور لوگوں کی کشش اور توجہ کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فورگراؤنڈنگ زبان کے مخصوص و منفرد اور انوکھے استعمال اور اظہار کے نت نئے طریقوں اور پیرایوں ، نیز زبان میں ندرت، جدت اور تازہ کاری کے عمل سے ہی معرضِ وجود میں آتی ہے، مثلاً کوئی عورت اگر یہ کہتی ہے کہ ’ Ten years ago I was very beautiful‘(=دس سال قبل میں بیحد خوب صورت تھی) تو یہ زبان کا عام اور خود کارانہ استعمال ہو گا، لیکن وہی عورت اگر یہ کہے کہ ’Two husbands ago I was very beautiful‘(=دو شوہروں ]سے شادی[سے قبل میں بیحد حسین تھی ) یا وہ یہ کہتی ہے کہ’Three children ago I was very young’ (=تین بچوں ]کی پیدائش [سے قبل میں نہایت جوان تھی) تو یہ زبان کا شعوری اور غیر خود کارانہ استعمال ہو گا۔ زبان کے اسی نوع کے استعمال کے لیے مکارودسکی نے ’فورگراؤنڈنگ‘ کی اصطلاح وضع ہے، کیوں کہ زبان کا یہی مخصوص استعمال لوگوں کی کشش اور توجہ کا باعث بنتا ہے۔ مذکورہ جملوں میں ’Two husbands ago‘ اور ’Three children ago‘ انوکھے اظہاری پیرایے (Uncommon expressions) ہیں۔ ممتاز انگریزی شاعر ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ (T. S. Eliot) اپنی شعری تخلیق ’’The Waste Land‘‘ میں کہتا ہے:
"The nymphs are departed
Departed, have left no addresses” .
یہاں بھی فورگراؤ نڈنگ کا عنصر غالب ہے، کیوں کہ nymphsاور addressesغیر عقلی انسلا کات ہیں۔
جدید اردو شاعروں نے فورگراؤ نڈنگ کو ایک موثر اظہاری پیرایے کے طور پر برتا ہے جس سے نہ صرف ان کی تخلیقی قوت اور جدتِ طبع کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ اظہار کے نادر اور انوکھے طریقوں کی تلاش اور کرتا ہے تو وہ بالارا نت نئے لسانی سانچوں کی تشکیل، نیز زبان کی تازہ کاری کے عمل سے ان کی غیر معمولی دل چسپی کا بھی پتا چلتا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں :
چلو آنکھوں میں پھر سے نیند بوئیں
کہ مدت سے اسے دیکھا نہیں ہے
(شہر یار)
نہ جانے کیوں درو دیوار ہنس پڑے اے شاذؔ
خیال آیا تھا اک روز گھر سجانے کا
(شاذ تمکنت)
آنکھ بھی برسی بہت بادل کے ساتھ
اب کے ساون کی جھڑی اچھی لگی
(احمد فراز )
اِن اشعار میں علی الترتیب ’آنکھوں میں نیند بونا‘، ’در و دیوار کا ہنس پڑنا‘، اور ’آنکھ کا برسنا‘ فورگراؤنڈنگ کی عمدہ مثالیں ہیں۔
(۶)
روسی ہیئت پسندوں اور پراگ اسکول کے ماہرینِ لسانیات نے ادب کے معروضی مطالعے کی بنیاد ڈالی تھی جس کے تحت ادبی متن کو خود مکتفی مان کر اس کا تجزیہ معروضی انداز سے کیا جاتا تھا۔ اس تجزیے کے دوران مصنف اور اس کے عہد، نیز دیگر خارجی عوامل سے صرفِ نظر کرتے ہوئے صرف متن پر توجہ مرکوز کی جاتی تھی۔ اس ضمن میں رومن جیکب سن، وکٹر شکلوو سکی اور مکا رووسکی کی خدمات لائقِ ستایش ہیں۔ مطالعۂ ادب کے معروضی نظریے ہی سے تحریک پا کر عملی تنقید (Practical Criticism)، نئی تنقید (New Criticism) اور براہِ راست لسانیات سے تعلق رکھنے والی شاخ اسلوبیات (Stylistics) کا ارتقا عمل میں آیا۔ ادب کی تنقید کے یہ تینوں نئے نظریات لسانی مضمرات سے مبرا نہیں۔ (۷)
نئی تنقید روسی ہیئت پسندی ہی کی طرح معروضی تھی اور ادبی متن کو خود مختار و خود کفیل اکائی تسلیم کرتی تھی، اور مصنف کے سوانحی کوائف اور تاریخی حوالوں سے صرفِ نظر کرتے ہوئے اپنی ساری توجہ صرف اس کی قرأت اور تجزیے پر صرف کرتی تھی۔ نئی تنقید کی تحریک انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل کے روایتی رویوں کے ردِ عمل کے نتیجے میں پہلی جنگِ عظیم (۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ء) کے خاتمے کے بعد ابھری تھی۔ اُس عہد کے اینگلو امریکی شاعروں اور ناقدوں نے اس تحریک کو جلا بخشی جن میں ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ (T. S. Eliot)، آئی۔ اے۔ رچرڈز(I. A. Richards)، ایف۔ آر۔ لیوس (F. R. Levis)، ولیم امپسن (William Empson)، اور جان کرو رینسم (John Crowe Ransom) کے نام خصوصیت کے ساتھ قابلِ ذکر ہیں۔ (۸)
ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ کے نزدیک کسی نظم یا ادبی متن کی حیثیت ایک لسانی/ لفظی فن پارے (Verbal artifact) کی تھی جسے وہ خود کفیل مانتا تھا، اور اس کے مصنف کی شخصیت اور تاریخی تناظر سے اسے الگ کر کے معروضی انداز سے جانچنے کے حق میں تھا، تبھی نظم کے معنی کا ادراک ممکن ہے۔ آئی۔ اے۔ رچرڈز نئی تنقیدی تحریک کا ایک دوسرا اہم نقاد گزرا ہے جس نے نئی تنقید کو ایک نئی جہت دی اور نظم کے معروضی تجزیاتی مطالعے سے اپنے شاگردوں کو عملی تنقید کی راہ دکھائی۔ (۹) رچرڈز نے عملی تنقیدی عمل کے دوران نظم کو خود کفیل و با اختیار اکائی مان کر اس کے مصنف کے سوانحی و تاریخی حوالوں سے صرفِ نظر کرتے ہوئے اس کی (ادبی متن کی) زبان پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔ اس نے شعری ترسیل کے لیے زبان کے محسوساتی (Emotive) پہلو پر زور دیا جس کا سائنسی زبان میں فقدان پایا جاتا ہے۔ رچرڈز نے اپنی عملی تنقید کی تکنیک میں معنی کی ترسیل کے سلسلے میں چار چیزوں کی اہمیت پر زور دیا ہے: ۱- مفہوم (Sense)، ۲-احساس (Feeling)، ۳-لہجہ (Tone)، اور ۴-مقصد(Intent)۔
نئی تنقید کے بنیاد گزاروں میں ایک اور اہم نام ایف۔ آر۔ لیوِ س کا ہے جس نے اپنے سہ ماہی رسالے Scrutiny کی وجہ سے ادبی دنیا میں غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ یہ رسالہ نہ صرف انگلستان، بلکہ امریکہ میں بھی بیحد مقبول ہوا۔ لیوس نے ادبی متن کے مطالعے اور تجزیے کے لیے ایک انوکھا طریقہ ایجاد کیا جو ’کلوز ریڈنگ‘ (close reading) کہلایا۔ اس کی تحریک اسے رچرڈز کی عملی تنقید کی تکنیک سے ملی۔ اس طریقِ کار میں نظم کے صرف عمیق مطالعے سے سروکار رکھا گیا اور ماورائے نظم کسی بھی نکتے، پہلو F.R. Leaھ کا برسنا‘ فورگر یا امر کو خارج از مطالعہ قرار دیا گیا۔ لفظی تجزیاتی مطالعے کا ایک اور انداز ایک دوسرے نقاد ولیم امپسن کے یہاں پایا جاتا ہے جو رچرڈز کا شاگرد تھا اور شاعر بھی تھا۔ اس نے رچرڈز کے شعری ترسیل سے متعلق محسوساتی زبان کے نظریے سے تحریک پا کر اپنا ایک منفرد نظریۂ ابہام (Theory of Ambiguity) تشکیل دیا۔ اس کا موقف تھا کہ شاعری کی زبان (جو عام بول چال یا سائنس کی زبان سے مختلف ہوتی ہے) محسوساتی ہونے کے ساتھ ساتھ مبہم (Ambiguous) بھی ہوتی ہے۔ امپسن نے اس نکتے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابہام کی سات قسمیں بیان کیں اور اس کی پیچیدہ مثالیں پیش کیں جن کی وجہ سے شاعری مبہم اور کثیرا لمعنی (Polysemous) بن جاتی ہے۔ (۱۰)
اسلوبیات ادب کے لسانیاتی مطالعے کا نام ہے۔ ادبی اسکالرز اسے ’اسلوبیاتی تنقید‘ کے نام سے یاد کرتے ہیں ، لیکن ماہرینِ لسانیات اسے ’اسلوبیات‘ یا ’لسانیاتی اسلوبیات‘ ہی کہنا پسند کرتے ہیں۔ اسلوبیات یا اسلوبیاتی تنقید کا ارتقا اطلاقی لسانیات (Applied Linguistics) کی ایک شاخ کے طور ۱۹۶۰ء کے آس پاس عمل میں آیا۔ اس میں لسانیات کی نظری بنیادوں (Theoretical Foundations) اور اصطلاحوں سے کام لیا جاتا ہے، نیز لسانیاتی طریقِ کار (Methodology)کو بروئے عمل لاتے ہوئے لسانیات کی تمام سطحوں (صوتی، صرفی، نحوی، معنیاتی، قواعدی) پر متن کے اسلوبیاتی تجزیے کا کام سر انجام دیا جاتا ہے۔ (۱۱)
اسلوبیاتی تنقید میں ادبی متن کے اسلوبی خصائص (Style-features) کی شناخت و دریافت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ متن کے لسانیاتی تجزیے کے بعد اسلوبیاتی نقاد اس کے اسلوبی خصائص کا پتا لگاتا ہے۔ مختلف فن پاروں میں مختلف نوع کے اسلوبی خصائص پائے جاتے ہیں ، مثلاً صوتی خصائص، صرفی خصائص، نحوی خصائص، وغیرہ- اقبالؔ کی نظم ’’ایک شام‘‘ اسلوبیاتی سطح پر صوتی خصائص کی بہترین مثال پیش کرتی ہے جس میں صفیری آوازوں (Fricative sounds)، مثلاً س، ش، خ، ف، غ کی تکرار وتکرر (Frequency) اور ان کی بُنت نظم کے مجموعی تاثر کو بہ خوبی اجاگر کرتی ہے۔ ادبی فن پارے کے اسلوبی خصائص کی شناخت و دریافت ہی اسلوبیاتی تنقید کا ماحصل ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک فن پارے کو دوسرے فن پارے سے یا ایک مصنف کو دوسرے مصنف سے ممیز کرسکتے ہیں۔ (۱۲)
اسلوبیاتی تنقید نظری و عملی اعتبار سے ادبی تنقید سے بیحد مختلف ہے۔ ادبی تنقید داخلی اور تاثراتی ہوتی ہے۔ اس میں وجدان سے کام لیا جاتا ہے اور اقداری فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ تنقید مصنف اور اس کے عہد کے اردگرد گھومتی ہے اور خارجی عوامل کا سہارا لیتی ہے۔ علاوہ ازیں اس کا انداز تشریحی ہوتا ہے۔ اس کے علی الرغم اسلوبیاتی تنقید معروضی ہوتی ہے۔ اس میں مشاہدے (Observation) سے کام لیا جاتا ہے، نہ کہ وجدان سے۔ اس میں فن پارے کے تجزیے کی بنیاد پر نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اسلوبیاتی تنقید کسی فن پارے کو اچھا یا برا نہیں کہتی، بلکہ اس کے خصائص بیان کر دیتی ہے جنھیں ہم اسلوبی خصائص (Style-features) کہتے ہیں۔ اس نظریۂ تنقید میں نہ تو مصنف کی ذات اہم ہوتی ہے اور نہ اس کا عہدیا دیگر خارجی عوامل۔ ان تمام باتوں سے اسلوبیاتی تنقید کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ اس کے نزدیک صرف ادبی فن پارے یا متن کی اہمیت ہوتی جسے خود مکتفی مان کر اسلوبیاتی نقاد اس کا مطالعہ و تجزیہ کرتا ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کا طریقِ کار توضیحی (Descriptive) ہوتا ہے، نہ کہ تشریحی جس میں تشریحی عمل کے دوران اکثر متن سے باہر کی چیزوں سے سروکار رکھا جاتا ہے۔
حواشی
۱- ’سوزِ وطن‘ منشی پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ تھا جو نواب رائے کے نام سے ۱۹۰۸ء میں زمانہ پریس، کانپور سے شائع ہوا تھا، لیکن دو سال بعد ہی اسے سرکاری طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا اور اس کے تمام دستیاب شدہ نسخے ’’بحقِ سرکار‘‘ ضبط کر لیے گئے تھے۔
۲- ’انگارے‘ سجاد ظہیر، احمد علی، رشید جہاں اور محمود الظفر کی لکھی ہوئی دس کہانیوں کا مجموعہ تھا جو ۱۹۳۲ء میں شائع ہوا تھا، لیکن شدید ردِ عمل کی وجہ سے اسے ضبط کر لیا گیا تھا۔ بقولِ خلیل الرحمن اعظمی ان مصنفین کے یہاں ’’قدیم معاشرے اور اخلاق و قوانین کے خلاف ایک وحشیانہ بغاوت ہے۔ ‘‘ دیکھیے خلیل الرحمن اعظمی، ’اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک‘ (علی گڑھ: انجمن ترقی اردو ]ہند[، ۱۹۷۲ء)، ص ۲۰۸۔
۳- ملاحظہ ہو رولاں بارت (Ronald Barthes) کا مقالہ”The Death of the Author” مشمولہ Image, Music, Text(از رولاں بارت)، ترجمہ: اسٹیفن ہیتھ (لندن: فونٹا نا پیپر بیکس، ۱۹۷۷ء)۔
۴- فرڈی نینڈ ڈی سسیور (Ferdinand de Saussure) کے فلسفۂ لسان سے متعلق مباحث کے لیے ملاحظہ ہو اس کی کتاب Course in General Linguistics (لندن: فونٹانا، ۱۹۷۴ء)۔
۵- روسی ہیئت پسندی اور نئی تنقید سے متعلق مباحث کے لیے دیکھیے ای۔ ایم۔ ٹامسن (E. M. Thompson)کی کتاب Russian Formalism and Anglo-American New Criticism (1971).
۶- فور گراؤنڈنگ کی تھیوری کے لیے دیکھیے جان مکارووسکی (Jan Mukarovsky) کا مقالہ Standard Language and Poetic Language” مشمولہ Linguistics and Literary Style، مرتبہ ڈونلڈ سی۔ فریمن (نیویارک: ہالٹ، رائن ہارٹ اینڈ ونسٹن، ۱۹۷۰ء)۔
۷- اِن تنقیدی مباحث کے لیے دیکھیے ڈبلیو۔ کے۔ ومسیٹ (جونیر)، اور کلینتھ بروکس (W. K. Wimsatt, Jr. , and Cleanth Brooks) کی تصنیف Literary Criticism: A Short History (ینویارک، ۱۹۵۷ء)
۸- مزید بحث کے لیے دیکھیے جان کرو رینسم (John Crowe Ransom) کی تصنیف The New Criticism (1941).
۹- مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے آئی۔ اے۔ رچرڈز کی تصنیف Practical Criticism (لندن، ۱۹۲۹ء)
۱۰- مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے ولیم امپسن (William Empson)کی تصنیف Seven Types of Ambiguity(لندن، ۱۹۳۰ء)۔
۱۱- اُردو میں اسلوبیات / اسلوبیاتی تنقید کے موضوع پر سب سے پہلے مسعود حسین خاں نے خامہ فرسائی کی۔ اسی لیے انھیں اسلوبیاتی تنقید کا بنیاد گزار کہا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو راقم السطور کامضمون ’’مسعود حسین خاں اور اسلوبیات ‘‘، مشمولہ’ تنقید اور اسلوبیاتی تنقید‘ از مرزا خلیل احمد بیگ (علی گڑھ: شعبۂ لسانیات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ۲۰۰۵ء)۔
۱۲- اسلوبیاتی تنقید کی نظری بنیادوں اور اسلوبیاتی تجزیوں کے لیے دیکھیے راقم السطور کی کتاب ’زبان، اسلوب اور اسلوبیات‘، دوسرا ایڈیشن (دہلی : ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، ۲۰۱۱ء)۔
٭٭٭
فراقؔ گورکھپوری کی سنگھار رس کی شاعری
(فراق گورکھپوری ]م: ۱۹۸۲ء[کو ان کی ۳۰ ویں برسی پر یاد کرتے ہوئے)
فراق گورکھپوری(۱۸۹۶تا ۱۹۸۲ء) کے بارے میں اکثر نقادوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ وہ ’’جدید حسیّت ‘‘ اور ’’نئے تہذیبی شعور‘‘ کے شاعر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فراق کی شاعری میں ایک نئے طرزِ احساس اور نئے لب و لہجے کا پتا چلتا ہے، لیکن فراق کے یہاں ہمیں جو چیز سب سے زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہے وہ ان کا ہندی اسلوب اور ان کی شاعری کی ہندوستانی فضا ہے۔ فراق نے اپنی شاعری میں ہندو اساطیر و تلمیحات کا ذکر جس کثرت سے کیا ہے اس کی مثال اردو شاعری میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ان کی شاعری میں ہندوستان کی مِٹی، یہاں کی بوباس، فضا اور تہذیب و معاشرت، نیز رسم و رواج کی جھلکیاں بھی خوب دیکھنے کو ملتی ہیں۔ فراق نے اپنے طرزِ بیان کا انتخاب بھی موضوع ہی کی مناسبت سے کیا ہے اور اپنی شاعری کی ہندوستانی فضا کی عکاسی کے لیے ہندی لفظیات، ہندی تشبیہات و استعارات اور ہندی علائم کا کثرت سے استعمال کیا ہے۔
فراق کے یہاں ہندوستانی عناصر اور ہندی لغات کی کار فرمائی یوں تو جگہ جگہ نظر آتی ہے، لیکن ان کی ’روپ‘ کی رباعیاں کلیتہً اسی رنگ میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ’روپ‘ کی رباعیوں کو فراق نے ’’سنگھار رس کی رباعیاں ‘‘ کہا ہے۔ یہ رباعیاں فراق نے جوش ملیح آبادی (۱۸۹۸ تا ۱۹۸۲ء) سے ’’ان بن ‘‘ ہو جانے کے بعد ۱۹۴۵ء کے امل ہیں۔ (۳) اگر فراق کی بات سے اتفاق کریں تو ان رباعیوں میں —
’’لطیف، نازک، رچے ہوئے اور مہذب انداز سے اپنی پوری وجدانی اور جمالیاتی شان سے ہندستان کی زندگی اور ہندستان کے کلچر کی مصوری یا ترجمانی ہوئی ہے۔ ‘‘ (۴)
فراق نے اردو شاعری میں ہندوستانیت کے فقدان کا اکثر ذکر کیا ہے، اور اردو شاعری کے ہندوستانی شاعری نہ بن سکنے پر اظہارِ افسوس کیا ہے۔ ان کے خیال میں ہندوستانیت کے کچھ عناصر شروع میں بعض دکنی شعرا کے یہاں ضرور نظر آئے، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی جھلک میر تقی میرؔ، نظیر اکبر آبادی، اور حالیؔ کے یہاں نظر آئی۔ اقبال کے دورِ اول کے کلام میں بھی ہندوستانیت کی جھلک نظر آئی، لیکن انھیں اس بات کا ہمیشہ افسوس رہا کہ ہندوستانی کلچر اپنے رچاؤ اور اپنی تمام قیمتی قدروں کے ساتھ اردو شاعری میں کہیں جلوہ گر نہ ہوسکا۔ فراق کے نزدیک ہندوستانی شاعری سے مراد ایسی شاعری ہے جس میں :
’’یہاں کی فضا کی ٹھنڈک اور گرمی ہو، ہندستان کی مٹی کی خوشبو ہو، یہاں کی ہواؤں کی لچک ہو جو یہاں کے آکاش، سورج، چاند اور ستاروں کا آئینہ بنے اور ان کو آئینہ دکھائے جس میں وہ مخصوص احساسِ حیات و کائنات ہو جو کہ ’رگ وید‘ سے لے کر تلسی داس اور سور داس اور میرا بائی کے کلام میں نظر آتا ہے جو اس زمانے میں بھی ٹیگور کے نغموں کی پنکھڑیوں کی آبیاری اور شادابی کا باعث ہے۔ ‘‘ (۵)
چوں کہ یہ تمام خوبیاں اردو شاعری میں پورے طور پر جلوہ گر نہ ہوسکیں، اس لیے اردو شاعری سے، اس کی تمام اچھائیوں کے باوجود، فراق کا ذہن کسی قدر ’’نا آسودہ‘‘ رہا۔ غالباً اسی ’’ناآسودگی‘‘ کے احساس کو ختم کرنے کے لیے انھوں نے ’روپ‘ کی رباعیاں] =سنگھار رس کی رباعیاں [تخلیق کیں۔
فراق اردو شاعری کو ہندوستانی کلچر اوراس کی روح کا ’’صحیح نمائندہ‘‘ اور ’’آئینہ دار ‘‘ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس کے لیے ان کے خیال میں، ’’اردو کو سنسکرت اور ہندی شاعری دونوں کی قدروں سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ ‘‘ فراق نے اپنی تنقیدی کتاب ’اردو کی عشقیہ شاعری ‘ میں بھی اس مسئلے پر اظہارِ خیال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :
’’اردو زبان ہندو، مسلمانوں کی مشترکہ زبان ضرور ہے، لیکن اردو ادب اُس وقت صحیح معنوں میں ہندو، مسلمانوں کا مشترکہ ادب ہو گا جب اردو لغت اور اردو ادب میں کافی تعداد سنسکرت کے فقروں اور ٹکڑوں بلکہ کبھی کبھی سنسکرت ترکیبوں کی بھی سلیقے سے جوڑ لی جائے۔ ‘‘ (۶)
(۲)
جیسا کہ سطورِ بالا میں کہا گیا ہے، فراق نے ’روپ‘ کی رباعیوں کو سنگھار رس کی رباعیاں کہا ہے۔ انھوں نے سنسکرت لفظ ’’روپ‘‘ کو جمالیاتی معنی میں استعمال کیا ہے۔ (۷) جمالیات یا جمالیاتی تجربے کا’کام‘ (काम)یعنی محبت کے جذبے سے گہرا تعلق ہے، اور ’کام ‘ کو سنگھار رس میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ لفظ ’سنگھار‘ سنسکرت زبان کے لفظ ’شرنگار‘ (श्रृंगार) سے مشتق ہے جو دو لفظوں ’شرنگ‘(श्रृंग)اور ’آر‘ (आर) کی سَندھی یعنی ترکیب سے بنا ہے۔ سنسکرت میں ’شرنگ‘ کے معنی ہیں ’کام‘ یعنی محبت اور ’آر‘ کے معنی ہیں ابھارنے، جگانے یا بیدار (Stimulate) کرنے والا۔ اس طرح ’شرنگار‘ سے مراد وہ تجربہ یا عمل ہے جو محبت کے جذبے کو ابھارتا، جگاتا یا بیدار کرتا ہے یا اس میں تحریک پیدا کرتا ہے۔ ہندواساطیر میں ’کام دیو‘ (कामदेव)کو محبت کا دیوتا مانا گیا ہے اور اس کی بیوی کو جس کا نام ’رتی‘ (रति) ہے، ’پرم روپ وَتی‘ یعنی انتہائی حسین و جمیل عورت کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ ’رتی‘ ادب و شاعری میں محبت اور حسن کا استعارہ بن گیا ہے۔ محبت انسان کا ایک ’استھائی بھاؤ‘ (स्थायी भाव) یعنی مستقل یا بنیادی جذبہ ہے جسے ’رتی‘ کہا گیا ہے۔ شرنگار رس =)سنگھار رس(کی بنیاد اسی جذبے پر قائم ہے۔ یہ سب سے اہم بنیادی جذبہ تسلیم کیا گیا ہے۔
سنگھار رس ان آٹھ رسوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر سنسکرت شعریات میں پایا جاتا ہے۔ یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ ’رس‘ (रस) اُس ’آنند‘ یعنی حظ کو کہتے ہیں جو کسی جمالیاتی تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تعلق در حقیقت انسان کے بنیادی جذبوں یا ذہنی کیفیات سے ہے جن کی تعداد آٹھ بتائی گئی ہے۔ (۸) ’رس‘ انھی جذبات کی جمالیاتی تجسیم ہے، اور سنگھار رس وہ حظ، مسرت یا آنند ہے جو محبت کے جمالیاتی تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ فراق نے سنگھار رس کو جمالیات کا مترادف مانا ہے۔ چنانچہ وہ ’روپ‘ کے دیباچے (’’چند باتیں ‘‘) میں لکھتے ہیں :
’’یہ رباعیاں سب کی سب جمالیاتی یا سنگھار رس کی ہیں۔ ‘‘ (۹)
سنسکرت شعریات میں سنگھاررس کے تین پہلو (Aspects) بیان کیے گئے ہیں : ’آلمبن‘ (आलम्बन)، ’آشرے‘ (आश्रय) اور ’اُدّی پن‘ () جن کا تفصیل سے ذکر آئندہ صفحات میں کیا جائے گا۔
فراق نے ’اردو کی عشقیہ شاعری‘ میں ان رباعیوں کا موضوع ’’جسم و جمالِ محبوب‘‘ بتایا ہے۔ (۱۰) اس میں کوئی شک نہیں کہ ان رباعیوں کو پڑھتے وقت نسوانی حسن و جمال کا احساس شدید تر ہو جاتا ہے اور قاری ایک ایسے جمالیاتی تجربے سے گذرتا ہے جس سے اسے حد درجہ روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ شکیل الرحمن نے ’روپ‘ کی رباعیوں کو ایک جمالیاتی مسلک سے تعبیر کیا ہے۔ وہ فراق کی جمالیات پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
’’روپ کی رباعیاں ایک جمالیاتی مسلک (Cult) کی بنیاد رکھتی ہیں۔ ہم اسے اردو شاعری میں ایک ایسے منفرد جمالیاتی مسلک سے تعبیر کر سکتے ہیں جو انفرادی طور پر ایک مختلف انداز سے جمالیاتی آسودگی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ الگ تھلگ رہ کرمسرتوں کو پانے اور لذتوں کو حاصل کرنے کا یہ مسلک جدید اردو شاعری میں اپنی نوعیت کا واحد مسلک ہے۔ ‘‘ (۱۱)
’روپ ‘ کی بعض رباعیوں میں فراق نے محبوب کے ’’جسم و جمال‘‘ کا ذکر اتنے بر ملا انداز میں کیا ہے کہ اس میں شہوانی (Erotic) جذبے کی لپک پیدا ہو گئی ہے، اور اس کی حدیں عریانیت سے جا ملتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فراق اپنے تخلیقی اظہار کے وسیلے سے جمالیاتی حظ کے علاوہ جنسی تلذذ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شکیل الرحمن راقم السطور کے اس خیال سے متفق نظر آتے ہیں، بلکہ وہ اس سے بھی آگے کی بات کہتے ہیں :
’’فراق نے اپنی رباعیوں میں دل فریب اور لذت آمیز فضا خلق کی ہے اور اس تخلیقی فضا کا تقاضا تھا کہ ایک ایسا نسوانی پیکر خلق ہو جائے جس کے جسمانی وجود کی ایک سے زیادہ جہتیں گوشت پوست کے سچے احساس کے ساتھ جلوہ بن جائیں۔ ۔ ۔ عورت اور اس کے تعلق سے حسن اور سیکس کی لمساتی کیفیتوں نے متحرک خاکے، لکیریں اور رنگ فراہم کیے ہیں۔ اس وِژن کا رشتہ ان اعجاز آفریں جمالیاتی تجربوں سے جا ملتا ہے جن کی ارفع اور افضل صورتیں اجنتا، کھجورا ہو اور ایلورا میں ملتی ہیں۔ ‘‘ (۱۲)
’روپ‘ کی رباعیاں صرف جمالیاتی تجربوں ہی کی حامل نہیں ہیں، بلکہ ان سے فراق کے حسی، لمسی اور جنسی تجربوں کا بھی پتا چلتا ہے۔ ذیل کی رباعیاں ملاحظہ ہوں :
چڑھتی ہوئی ندّی ہے کہ لہراتی ہے
پگھلی ہوئی بجلی ہے کہ بل کھاتی ہے
پہلو میں لہک کے بھینچ لیتی ہے وہ جب
کیا جانے کہاں بہا کے لے جاتی ہے
(رباعی ۸۳)
کھنچنا ہے عبث، بغل میں بانہوں کو تولے
کھو جانے کا ہے وقت، تکلف نہ رہے
ہنگامِ وصال، کر سنبھلنے کی نہ فکر
سَو سَو ہاتھوں سے مَیں سنبھالے ہوں تجھے
(رباعی ۸۲)
پہلو کی وہ کہکشاں، نبتھوں ؎ کا ابھار
ہر عضو کی نرم لو میں مدھم جھنکار
ہنگامِ وصال پینگ لیتا ہوا جسم
سانسوں کی شمیم اور چہرہ گلنار
(رباعی ۸۱)
( ؎ نبتھوں = سرین ]فراقؔ [)
فراق نے یہ رباعیاں کسی قسم کی افادیت کے پیشِ نظر نہیں کہی ہیں۔ انھوں نے ’روپ ‘ کے دیباچے میں خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ ’’ان میں شاعری کے وہ افادی پہلو نظر نہیں آئیں گے جن کے لیے ہم لوگ بے صبر رہتے ہیں۔ ‘‘ لیکن وہ یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ احساسِ جمال، جنسی جذبے یا شہوانی نفسیات کی تہذیب اگر عشقیہ یا جمالیاتی شاعری کے ذریعے سے ہوسکے تو ایسی شاعری کو ’’بالکل غیر افادی ‘‘ قرار نہیں دیا جا سکتا۔
جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، ’روپ‘ کی رباعیاں ۱۹۴۵ء کے اوائل کی تخلیق ہیں۔ فراق نے اگرچہ اس سے پہلے بھی رباعیاں کہی ہیں جو ان کے مجموعۂ کلام ’روحِ کائنات‘ میں شامل ہیں، لیکن وہ سب کی سب روایتی انداز کی ہیں۔ ان کے الفاظ، ترکیبیں اور بندشیں قدیم طرز کی رباعیوں کی یاد دلاتی ہیں۔ مضامین اور خیالات کے اعتبار سے بھی ان میں کوئی نیا پن نہیں۔ اس کے علی الرغم ’روپ ‘ کی رباعیاں ایک نئے موڈ کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ ان میں تخیل کی ایک نئی دنیا آباد ہے، اور فکر نے اظہار کے نئے اسالیب اختیار کیے ہیں۔ فراق کے تخلیقی اظہار کو نیا موڑ دینے میں جوش ملیح آبادی کا نہایت اہم کردار رہا ہے۔ اسی لیے ان سے ’’ان بن ‘‘ کے باوجود ’روپ‘ کا انتساب فراق نے جوش کے نام کیا ہے۔
(۳)
’روپ ‘ کی رباعیوں کو موضوع کے اعتبار سے دو زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم ان رباعیوں کی ہے جن میں ہندوستان کے کلچر (بلکہ ہندو کلچر) اور آدابِ معاشرت، نیز یہاں کی سماجی اور گھر یلو زندگی کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فراق نے ان رباعیوں میں ہندوستانی معاشرے اور ہندو معاشرت کے بڑے دل آویز مرقعے اور یہاں کی گھر یلو زندگی کی بڑی خوبصورت تصویریں پیش کی ہیں جن میں عورت کے مختلف روپ اور انداز دیکھنے کو ملتے ہیں ؛ کہیں وہ الھڑ دوشیزہ ہے تو کہیں سہا گن اور گرہستن اور کہیں معصوم بچے کی ماں۔ اسی کے ساتھ ان رباعیوں میں یہاں کے موسم، دریا، گھاٹ، چاند، سورج، آکاش، گھٹا، پشوپکشی اور پھولوں کا بھی ذکر بڑے دل فریب انداز میں ملتا ہے۔
ان رباعیوں میں جو مرقعے پیش کیے گئے ہیں اور جن مناظر کی عکاسی کی گئی ہے ان میں سے بعض یہ ہیں، مثلاً مدھم سروں میں گانا، لوریاں سنانا، آرتی اتارنا، دیوی کا ستار بجانا، بلائیں لینا، چھم چھم ناچنا، گھر کی عورتوں کا بابل گانا، جھولا جھولنے میں ساون گانا، گھاٹ پر نہانا، الگنی پر گیلی ساڑی پھیلانا، تلسی پر پانی چڑھانا، ایکھ کے کھیتوں میں معصوم کنواریوں کا دوڑنا اور چھلانگ لگانا، چاندنی رات میں کشتی پر دریا کی سیر کرنا، بچے کو ہاتھوں پہ جھلانا، سہاگن کاسہاگ سیج پر سونا، گھر کی لکشمی کا بھوجن پکانا، سہاگنی کا تھال سجائے ہوئے آنا، دہی متھنا، ہولی کھیلنا، ماں کا بچے سے خفا ہونا، دیوالی کی شام گھروں کو سجانا، بھائی کے راکھی باندھنا، گائے کو چارا کھلانا، گائے کو دوہنا، پنگھٹ پر گگریاں چھلکنا، مندر میں چراغ کا جھلملانا، کوئل کا کوکنا، بھونروں کا منڈلانا، چندر ماسے امرت برسنا، گاتی ہوئی اپسرا کا گگن سے اترنا، بچے کو نہلانا/ کپڑے پہنانا، پانی کا ہچکولے لے کر ترنگ بھرنا، بھینچ کے چوم چوم لینا، گیسو سمیٹے نیند سے اٹھنا، بستر سے آنکھیں ملتی اٹھنا، پریم کے ترانے چھیڑنا، معصوم آنکھوں میں اشک چھلکنا، بادل کی تہوں سے ماہِ کامل کا نکلنا، گیسو کھولے کروٹ سے سونا، وغیرہ۔
ان رباعیوں میں پیش کیے گئے چند اور دل آویز مرقعے اور دل فریب مناظرو کیفیات ملاحظہ فرمائیں، مثلاً ساون کی پھوار، بنسی کی تان، چیت کی چاندنی، چندر مکھی کی مسکراہٹ، بسنت کی ترنگ، ماتھے کی کہکشاں، سرکتا گھونگھٹ، کھلتا ہوا کنول، موروں کا رقص، تاروں بھری رات، پائل کی صدا، چہرے کی دمک، منڈلا تی گھٹا، مہکتی ہوئی شام، گھنگھور گھٹا، گاتی ہوئی اپسرا، رس کی لہر، روپ کا کنوارا پن، تلووں کی گدگدی، فضا میں سات رنگوں کی پھوار، تاروں کا کارواں، نیند بھری انگڑائی، شبنم میں نہائی صبح، گلوں کے جھرمٹ میں جگنو کی چمک، وغیرہ:
تاروں بھری رات! بزمِ فطرت ہے سجی
ہے شوخ نگاہ میں بھی ایسی نرمی
یہ چندر کرن میں سات رنگوں کی جھلک
گاتی ہوئی اپسراگگن سے اتری
(رباعی ۱۱۳)
گنگا میں چوڑیوں کے بجنے کا یہ رنگ
یہ راگ، یہ جل ترنگ، یہ رَو، یہ امنگ
بھیگی ہوئی ساڑیوں سے کوندے لپکے
ہر پیکرِ نازنین کھنکتی ہوئی چنگ
(رباعی ۱۳۱)
حمّام میں زیرِ آب جسمِ جاناں
جگمگ جگمگ یہ رنگ و بو کا طوفاں
ملتی ہیں سہیلیاں جو منہدی رچے پاؤں
تلوؤں کی گدگدی ہے چہرے پہ عیاں
(رباعی ۱۴۲)
کس پیار سے دے رہی ہے میٹھی لوری
ہلتی ہے سڈول بانہہ گوری گوری
ماتھے پہ سہاگ، آنکھوں میں رس، ہاتھوں میں
بچے کے ہنڈولے کی چمکتی ڈوری
(رباعی ۲۶۹)
رخساروں پہ زلفوں کی گھٹا چھائی ہوئی
آنسو کی لکیر آنکھوں میں لہرائی ہوئی
وہ دل امڈا ہوا وہ پریمی سے بگاڑ
آواز غم و غصے سے بھرّائی ہوئی
(رباعی ۲۲۷)
(۴)
’روپ‘ کی دوسری قسم کی رباعیاں وہ ہیں جن کا انداز خالص جمالیاتی ہے اور جن میں عشقیہ جذبات اور جنسی خیالات کی ترجمانی کی گئی ہے۔ فراق نے محبوب کے نازو انداز، شرم و حیا، حسن و جمال اور شوخی و ادا سے لے کر اس کے جسم کے ایک ایک عضو کا ذکر ان رباعیوں میں کیا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا نسوانی عضوِ بدن ہو جس پر فراق کی شاعرانہ نظر نہ پڑی ہو۔ ان رباعیوں میں کہیں کہیں عریاں جنسی خیالات بھی در آئے ہیں جو شہوانی جذبات کو ہوا دیتے ہیں، لیکن اس میں فراق کا کوئی قصور نہیں کہ سنگھار رس کی شاعری میں اس قسم کی عریاں نگاری کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ مشہور ماہرِ جمالیات ابھینو گپت نے تو شرنگار رس کی تعریف ہی یہی کی ہے کہ یہ وہ ’’جذبہ‘‘ ہے ’’جو فرد کی جنس کو بیدار کرتا ہے۔ ‘‘ (۱۳)
شرنگار رس کی شاعری میں ’آلمبن ‘ (आलम्बन) کے تصور کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، بلکہ المبن ہی اس شاعری کا مرکزو محور ہے۔ یہ محبت کا مخرج و منبع ہے۔ ’کام‘ (काम) یعنی جذبۂ عشق (Love Instinct) اسی کو دیکھ کر بیدار ہوتا ہے۔ یہ ’سوندریہ‘ (सौन्दर्य) یعنی حسن و جمال کا پیکر سمجھا جاتا ہے۔ حسن اور محبت یا حسن اور عشق (Beauty and Love) میں گہرا رشتہ پایا جاتا ہے۔ نسوانی وجود میں یہ دونوں چیزیں اس طرح مدغم ہو جاتی ہیں کہ پتا ہی نہیں چلتا کہ محبت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور حسن کہاں ختم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جمالیاتی نقطۂ نظریہ ہے کہ عشق کی ابتدا حسن سے ہوتی ہے۔ عاشق پہلے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھ کر مبہوت و متحیر رہ جاتا ہے، پھر اس کے عشق میں سرشار و دیوانہ ہو جا تا ہے۔ ’آلمبن‘ کو ہم آسانی کی خاطر ’محبوب‘ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ سنگھار رس کی شاعری میں آلمبن یعنی محبوب کے نہ صرف حسن و جمال کی تعریف بیان کی جاتی ہے، بلکہ اس کے جسم کے اعضا کابھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے فراق نے ’روپ‘ کی رباعیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کا موضوع ’’جسم و جمالِ محبوب‘‘ ہے۔
اب ذرا محبوب کے ان اعضائے بدن پر ایک نظر ڈالیں جن کا ذکر ’روپ‘ کی رباعیوں میں ملتا ہے، مثلاً چہرہ، رخ، منہ، مکھڑا، سر، جبیں، پیشانی، ماتھا، ابرو، آنکھ، نین، پتلی، پلک، مژہ، مژگاں، رخسار، عارض، گال، گات (گال)، لب، ہونٹ، اَدھر (لب)، ناک، کان، ٹھوڑی، گردن، کلائی، شانہ، دوش، بغل، بازو، ہاتھ، بانہہ، انگلی، دل، سینہ، کاندھا، ناف، کمر، پیڑو، کولھا، ران، گھٹنا، پنڈلی، ٹخنہ، پاؤں، تلوا، ایڑی، وغیرہ۔ محبوب کے جسم و اعضا کے بیان کے ساتھ فراق نے محبوب کی آواز، گفتار، رفتار، چال، چاپ، انگڑائی، شوخی، مسکان، مسکراہٹ، تبسم، ہنسی، جماہی، دھڑکن، سانس، زلف، گیسو، مانگ، جوڑا، بال، پہلو، گود، نظر، نگاہ، آنسو، تِل، قامت، قد، رنگ، روپ، جوبن، اور جوانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ محبوب سے تعلق رکھنے والی بعض دوسری چیزوں مثلاً ساڑی، چولی، گھونگھٹ، آنچل، کنگھی، کنگن ور چوڑی کو بھی نہیں بھولے۔
فراق نے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتے وقت فارسی کی خوبصورت تراکیب کا بھی استعمال کیا ہے جن میں سے چند یہ ہیں، مثلاً روئے تاباں، جسمِ رنگیں، تنِ شفاف، تنِ نازک، گیسوئے شب گوں، شوخیِ نگہ، قدِرعنا، زلفِ پیچاں، پیکرِ نازنیں، وغیرہ۔
محبوب کا سراپا، اور اس کے حسن و جمال کی جھلک ان رباعیوں میں ملاحظہ فرمائیں :
مکھڑا دیکھیں تو ماہ پارے چھپ جائیں
خورشید کی آنکھ کے شرارے چھپ جائیں
رہ جانا وہ مسکراکے تیرا کل رات
جیسے کچھ جھلملا کے تارے چھپ جائیں
(رباعی ۱۳۳)
آواز میں وہ لوچ کہ بلبل چہکے
رفتار میں وہ موج کہ سبزہ لہکے
زلفوں سے چمک مانگتی ہے شامِ بہار
عارض میں حنا کا نرم شعلہ دہکے
(رباعی ۱۴۷)
وہ پینگ ہے روپ میں کہ بجلی لہرائے
وہ رس آواز میں کہ امرت للچائے
رفتار میں وہ لچک پون رس بل کھائے
گیسو میں وہ لٹک کہ بادل منڈلائے
(رباعی ۲۲)
انگڑائی سے نیند آفتابوں کو بھی آئے
وہ چال کہ ٹھوکرآسمانوں کو لگائے
وہ قد کہ جھنجھوڑ کر قیامت کو جگائے
وہ شوخ ادا کہ برق آنکھیں جھپکائے
(رباعی ۱۲۷)
امرت سے دھلی جبیں، ابرو کے ہلال
گردن کا یہ خم، یہ چھب، یہ حسنِ خدوخال
ہر عضو میں یہ لچک، یہ نکھ سُکھ کا رچاؤ
دب جاتا ہے صنعتِ اجنتا کا کمال
(رباعی ۱۳۰)
انسان کے پیکر میں اتر آیا ہے ماہ
قدیا چڑھتی ندی ہے امرت کی اتھاہ
لہراتے ہوئے بدن پہ پڑتی ہے جب آنکھ
رس کے ساگر میں ڈوب جاتی ہے نگاہ
(رباعی ۳)
شرنگار رس کی شاعری میں ’آلمبن‘ کے علاوہ ایک دوسرے انسانی وجود کا بھی حوالہ پایا جاتا ہے جسے ’آشرے‘ (vkJ;) کہتے ہیں۔ محبت کا جذبہ اسی کے دل میں بیدار ہوتا ہے اور عشق کی چنگاری یہیں بھڑک کر شعلہ بنتی ہے۔ سنگھار رس کی رباعیوں میں فراق نے محبت کے تجربات، عشق کی واردات اور عاشق، نیز عاشق کے دل پر گذرنے والی کیفیات کو نہایت دل فریب و دل آویز انداز میں بیان کیا ہے:
جب چاند کی وادیوں سے نغمے برسیں
آکاش کی گھاٹیوں میں ساغر اچھلیں
امرت میں دھلی ہو رات اے کاش ترے
پائے رنگیں کی چاپ ایسے میں سنیں
(رباعی ۱۶۹)
جس طرح ندی میں ایک تارا لہرائے
جس طرح گھٹا میں ایک کوندا بل کھائے
برمائے فضا کو جیسے اک چندر کرن
یوں ہی شامِ فراق تیری یاد آئے
(رباعی ۱۷۱)
جس طرح رگوں میں خونِ صالح ہو رواں
جس طرح حیات کا ہے مرکز رگِ جاں
جس طرح جدا نہیں وجود و موجود
کچھ اس سے زیادہ قرب اے جانِ جہاں
(رباعی ۱۷۵)
رنگت تری کچھ اور نکل آتی ہے
یہ آن تو حوروں کو بھی شرماتی ہے
کٹتے ہی شبِ وصال، ہر صبح کچھ اور
دوشیزگیِ جمال بڑھ جاتی ہے
(رباعی ۲۴۲)
سنگھار رس کی شاعری کا ایک اور اہم عنصر بھی ہے جسے ’اُدّی پن‘ () کہتے ہیں۔ اس سے مراد ماحول اور فضا کی رنگینی ہے جسے دیکھ کر دل میں امنگیں پیدا ہوتی ہیں اور محبت کے جذبات انگڑائیاں لینے لگتے ہیں۔ فراق نے ’روپ‘ کی رباعیوں میں ماحول کی خوب صورتی اور فضا کی رنگینی کا اکثر ذکر کیا ہے۔ ایسے میں انھیں محبوب کی یاد ستانے لگتی ہے اور اس سے ملنے کے لیے ان کا دل بے قرار ہو اٹھتا ہے:
جب کھول رہی ہوں پہلی کرنیں پلکیں
جب رات سمیٹتی ہو مہکی الکیں
جب ذرے کنمنا کے آنکھیں کھولیں
تیری آوازِ پا کے ساغر چھلکیں
(رباعی ۱۵۵)
جب تاروں کے کارواں ہوں ٹھہرے ٹھہرے
جب کشتیِ ماہِ نو ہو لنگر ڈالے
جب نیند کی سانس کہکشاں لیتی ہو
ایسے میں کاش تری آہٹ آئے
(رباعی ۱۵۸)
وہ اک گہرا سکوت کل رات گئے
طاقوں پہ دیے نیند میں ڈوبے ڈوبے
پلکیں جھپکا رہی تھیں جب ٹھنڈی ہوائیں
آنا ترا اک نرم اچانک پن سے
(رباعی ۱۵۳)
جب زلفِ شبِ تار ذرا لہرائی
جب تاروں نے پور انگلیوں کی چٹکائی
جب چاند کی بل کھائی جبیں ابھری ذرا
ایسے میں تری نیند بھری انگڑائی
(رباعی ۱۶۱)
جب تاروں نے جگمگاتے نیزے تولے
جب شبنم نے فلک سے موتی رولے
کچھ سوچ کے خلوت میں بصد ناز اس نے
نرم انگلیوں سے بند قبا کے کھولے
(رباعی ۱۵۶)
جب رات ہو جگمگاتی چادر اوڑھے
جب چاند کی آنکھ سے بھی غفلت ٹپکے
جب سازِ سکوت رات ہو ایسے میں
تیرے قدموں کی گنگناہٹ آئے
(رباعی ۱۶۳)
فراق نے اردو شاعری میں سنگھاررس کو جس طرح سے برتا ہے اور ’روپ‘ کی رباعیوں کی شکل میں جمالیاتی شاعری کے جو نمونے پیش کیے ہیں اس سے اردو شاعری، بالخصوص رباعی کی صنف کو ایک امتیازی شان حاصل ہوئی ہے، لیکن افسوس کہ اس باب میں فراق کا کوئی پیروکار پیدا نہ ہوا اور اردو شاعری میں سنگھار رس کی یہ روایت فراق کے ساتھ ہی ختم ہو گئی (قطع نظر جاں نثار اختر کے جنھوں نے ’گھر آنگن‘ کی مثال قائم کی)۔
حواشی
۱- فراقؔ گورکھپوری نے جوشؔ ملیح آبادی سے اپنی ’’ان بن‘‘ کا ذکر ’روپ‘ (۱۹۴۷ء) کے ’’انتساب ‘‘ میں کیا ہے جو ’’شاعرِ اعظم جوش ملیح آبادی کے نام‘‘ ہے۔ اس انتساب میں فراق نے جوش کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے:
’’جوشؔ،
کچھ دنوں کی بات ہے کہ میرٹھ کے مشاعرے سے ہم تم ساتھ ساتھ دلّی آئے اور ایک ہی جگہ ٹھہرے۔ رات باقی تھی، ہم لوگوں کے اور ساتھی ابھی سور ہے تھے، لیکن تھوڑ ے سے وقفے کے آگے پیچھے ہم تم جاگ اٹھے۔ باتیں ہونے لگیں۔ تم نے مجھ سے پوچھا کہ فراق تم رباعیاں نہیں کہتے؟ میں نے کہا: کبھی بہت پہلے کچھ رباعیاں کہی تھیں، ادھر تو نہیں کہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ بعد کو دلّی کے اس قیام میں مجھ سے تم سے اَن بن بھی ہو گئی تھی اور آپس میں تیز تیز باتیں بھی ہو گئی تھیں جس کی تکلیف ہم دونوں کو بہت دنوں تک رہی، شاید اب تک ہے۔ ‘‘ (’روپ‘، ص ۴-۳)
راقم السطور کا خیال ہے کہ فراق و جوش میں یہ ’’اَن بن ‘‘ غالباً ۱۹۴۴ء کے اواخر میں ہوئی ہو گی، کیوں کہ اس کے فوراً بعد فراق نے ’’جسم و جمالِ محبوب‘‘ پر رباعیاں کہنا شروع کیں جن کا مجموعہ ’روپ‘ کے نام سے شائع ہوا۔ فراق گورکھپوری اپنی تنقیدی کتاب ’اردو کی عشقیہ شاعری‘ میں ایک جگہ لکھتے ہیں :
’’میں نے جنوری، فروری ۱۹۴۵ء میں تین سورباعیاں جسم و جمالِ محبوب پر کہیں۔ ‘‘ (ص ۱۳۱)
۲- ’روپ‘ ]سِنگھار رس کی رباعیاں [، ناشر: سنگم پبلشنگ ہاؤس، الٰہ آباد، ۱۹۴۷ئ۔ (سیدہ جعفر نے اپنی کتاب ’فراق گورکھپوری‘ ]نئی دہلی: ساہتیہ اکادمی، ۱۹۹ء[ میں لکھا ہے کہ ’’۱۹۴۶ء میں ’روپ‘ کی اشاعت عمل میں آئی ‘‘ جو صحیح نہیں ہے۔ دیکھے متذکرہ کتاب کا، ص ۷۵)۔
۳- فراق نے ’’محبوب کے حسن سے متعلق ‘‘ لگ بھگ ’’چار سو‘‘ رباعیاں کہی تھیں، لیکن ’روپ‘ میں صرف ۳۵۱ رباعیاں ہی شامل کی گئیں۔ (دیکھیے ’اردو کی عشقیہ شاعری‘ ]فراق گورکھپوری [، ص ۱۴۱ ]حاشیہ[)۔
۴- دیباچہ ]’’چند باتیں ‘‘[، ’روپ‘ (فراق گورکھپوری )، ص ۷۔
۵- ایضاً، ص ۱۰-۹۔
۶- فراق گورکھپوری، ’اردو کی عشقیہ شاعری‘ (کراچی: مکتبۂ عزم و عمل، ۱۹۶۶ء)، ص ص ۱۲۸-۱۲۷۔
۷- ’’روپ‘‘ کے لغوی معنی حسن و جمال اور Beautyکے ہیں۔
۸- آٹھ بنیادی جذبے یہ ہیں : ۱) ’رتی‘ (محبت)، ۲) ’ہاس‘ (مزاح)، ۳) ’شوک‘ (غم)، ۴)’ کرودھ‘ (غصہ)، ۵) ’اُتساہ‘ (بہادری)، ۶) ’بھَے‘ (خوف)، ۷) ’جگپسا‘ (نفرت)، ۸) ’وِسمے‘ (حیرت واستعجاب)۔ انھی آٹھ بنیادی جذبوں کی بنیاد پر سنسکرت شعریات میں علی الترتیب آٹھ بنیادی رس بیان کیے گئے ہیں جو یہ ہیں : ۱) شرنگار رس =]سنگھار رس[، ۲) ہاسیہ رس، ۳) کرونا رس، ۴) رودر رس، ۵) ویررس، ۶) بھیانک رس، ۷) بیبھتس رس، ۸) اَدبھُت رس۔ سنسکرت کے بعض عالموں کا خیال ہے کہ بنیادی رسوں کی مجموعی تعداد نو ہے، لیکن نواں رس جو غالباً ’سنتارس‘ ہے متنازع فیہ ہے۔
۹- دیباچہ ]’’چند باتیں ‘‘[، ’روپ‘، ص ۱۴۔
۱۰- ’اردو کی عشقیہ شاعری‘، ص ۱۳۱۔
۱۱- شکیل الرحمن، ’ ’فراق کی جمالیات: ’روپ‘ کی رباعیاں ‘‘، مطبوعہ ہفت روزہ ’ہماری زبان‘ (نئی دہلی)، جلد ۵۵، شمارہ نمبر ۴۷-۴۶، (۸و ۱۵؍دسمبر ۱۹۹۶ء)، ص۱۔ ]کل ہند سہ روزہ سمینار کے موقع پر خصوصی پیش کش[۔
۱۲- ایضاً۔
۱۳- بہ حوالہ قاضی عبدالستار، ’جمالیات اور ہندوستانی جمالیات‘ (علی گڑھ: ادبی پبلی کیشنز، آنند بھون، ۱۹۷۷ء)، ص ۴۰۔
٭٭٭
ڈاکٹر فرمان فتح پوری اور نگارِ پاکستان
’’نگارِ پاکستان‘‘ کا نام ذہن میں آتے ہیں ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی تصویر سامنے آ جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو، ’’نگارِ پاکستان‘‘ سے ان کی تیس سالہ وابستگی نے دنوں کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بنا دیا ہے۔ فرمان صاحب کے بغیر نہ تو ’’نگارِ پاکستان‘‘ کا تصور ممکن ہے اور نہ ’’نگار پاکستان‘‘ کے بغیر فرمان صاحب کا۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے نیازؔ فتح پوری اور ’’نگارِ پاکستان‘‘ کے بارے میں ایک جگہ لکھا تھا کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی تحریک، ایک ہی مکتبۂ فکر اور ایک ہی رجحان کے دو نام ہیں، جنہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ؎۱ نیاز و نگار کے بارے میں شائع ہونے والے’’نگارِپاکستان‘‘ پر صادق آتا ہے۔
’’نگارِ پاکستان‘‘ دراصل اس ’’نگار‘‘ کا تسلسل ہے جو نیازؔ فتح پوری کی ادارت میں فروری۱۹۲۲ء میں آگرہ سے نکلتا رہا۔ اسی سال یہ لکھنؤ منتقل ہوا اور ۱۹۶۲ء تک یعنی نیاز صاحب کے پاکستان ہجرت کرنے تک یہ لکھنؤ سے شائع ہوتا رہا۔ ۱۹۶۲ء سے یہ کراچی سے نکلنا شروع ہوا اور آج تک نکل رہا ہے۔ ۱۹۶۶ء تک اس کے مدیر/مدیر اعلیٰ نیازؔ فتح پوری مقرر ہوئے اور آج تک وہی اس کے مدیر ہیں۔ اردو زبان و ادب کی اتنی طویل مدّت تک اور ایسی بے مثل خدمت اردو کے شاید ہی کسی رسالے نے انجام دی ہو۔ نیازؔ فتح پوری اردو کے ایک بلند پایہ اور بے مثل ادیب تھے۔ اگر وہ اردو میں کاوش نہ کرتے تب بھی محض ’’نگار‘‘ کے مدیر کی حیثیت سے اردو ادب و صحافت کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا۔
نیازؔ فتح پوری ایک سخت گیر مدیر تھے۔ انہوں نے اپنے رسالے کا ایک خاص معیار تا دم آخر قائم رکھا۔ ان کی کسوٹی پر پورا اترنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ہر کس و ناکس ’’نگار‘‘ میں چھنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ ’’نگار‘‘ میں چھنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی اور جو چیز چھپ جاتی اسے استناد کا درجہ حاصل ہو جاتا تھا اور ہر طرف اس کی دھوم مچ جاتی تھی۔ خلیل الرحمن اعظمی کے آتشؔ پر مقالے کو اس وجہ سے بھی غیر معمولی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی کہ وہ سب سے پہلے ’’نگار‘‘ میں چھپا جسے پڑھ کر فراقؔ گورکھپوری نے انہیں تہنیتی خط لکھا اور رشید احمد صدیقی نے انہیں ’’ آتش پرست‘‘ کے خطاب سے نوازا۔ یہ صرف ایک مثال ہے اسی طرح نہ جانے کتنے اربابِ قلم نے ’’نگار‘‘ کی بدولت معتبر نقّاد اور مستند ادیب و شاعر کا مرتبہ حاصل کیا۔ ’’نگار‘‘ کے سلسلے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ صرف ادب اور ادبی مسائل تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اس میں چھپنے والی تخلیقات مختلف علوم کا احاطہ کرتی تھیں مثلاً ادب، شاعری، افسانے اور ڈرامے کے علاوہ اس میں فنونِ لطیفہ، تاریخ، سیاحت، جغرافیہ، سیاسیت و ہئیت اور طب پر بھی مضامین شائع ہوتے تھے۔ ’’نگار‘‘ کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ اس کے خاص نمبر یا سالنامے بڑی پابندی کے ساتھ ہر سال نکلا کرتے تھے اور یہ سلسلہ نیاز صاحب نے۱۹۲۸ء میں مومنؔ نمبر کے اجراء سے شروع کیا تھا جو ان کے دم آخر یں تک قائم رہا( اور آج بھی قائم ہے)’’نگار‘‘ کے بعض خاص نمبر انہوں نے خود تحریر کیے مثلاً پاکستان نمبر(۱۹۴۸ء) فرماں روایانِ اسلام نمبر(۱۹۵۴ء) علوم اسلامی و علمائے اسلام نمبر(۱۹۵۵ء)، معلومات نمبر۱۹۵۸ء) غالبؔ نمبر(۱۹۶۱ء) خود ان کے تحریر کردہ ہیں۔ ان کے علاوہ جن موضوعات پر خاص نمبر شائع ہوئے ان میں اردو شاعری، ہندی شاعری، اصحابِ کہف، خود نوشت، جدید شاعری، قرآن، انتقاد، افسانہ، مستقبل کی تلاش، اصنافِ سخن، انشائے لطیف وغیرہ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ مومنؔ، بہادر شاہ ظفرؔ، مصحفیؔ، نظیرؔا کبرآبادی، ریاضؔ خیرآبادی، حسرتؔ موہانی، داغؔ دہلوی، غالبؔ، جگرؔ مرادآبادی، اور اقبالؔ جیسے شعرا پر بھی ’’نگار‘‘ کے خصوصی نمبر شائع ہوئے۔ ان میں سے بیشتر کی آج بھی وہی اہمیت ہے جو پہلے تھی ؎۳ ’’نگار‘‘ کی ۱۹۲۲ء تا ۱۹۶۲ء کی فائلوں کے سرسری جائزے سے پتا چلتا ہے کہ اس دور کے تمام مشاہیر ادب کی نگار شات اس میں چھپتی رہی ہیں۔ اس دور کا شاید ہی کوئی بڑا ادیب و شاعر ہو جس کی تخلیق ’’نگار‘‘ کے صفحات کی زینت نہ بنی ہو۔ ’’نگار‘‘ کے اس پس منظر کے بعد اب ہم ’’نگار پاکستان‘‘ کی طرف آتے ہیں۔
جولائی ۱۹۶۲ء میں نیازؔ فتح پوری کے پاکستان ہجرت کرنے کے بعد سے ’’نگار‘‘ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس کی پہچان ’’نگارِ پاکستان‘‘ کے نام سے قائم ہوتی ہے اور ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری بطور اعزازی اس سے منسلک ہوتے ہیں۔ اردو رسائل کے سلسلے میں بالعموم ہی دیکھا گیا ہے کہ رسالے کی عمر اس کے مدیر کی عمر کی عشرِ عشیر بھی نہیں ہوتی۔ بسا اوقات اپنے مدیر کی رحلت کے ساتھ ہی وہ رسالہ بھی دم توڑ دیتا ہے، لیکن ’’نگار پاکستان‘‘ کی یہ خوش نصیبی رہی ہے کہ نیازؔ فتح پوری کے انتقال (۱۹۶۶ء) کے۲۷ سال بعد بھی یہ رسالہ زندہ و تابندہ ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اسے نیازؔ فتح پوری کے بعد فرمانؔ فتح پوری جیسا لائق مدیر ملا۔
ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے ’’نگار پاکستان‘‘ کی ترتیب کا کام نومبر۱۹۶۲ء میں سنبھالا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نیازؔ فتح پوری لکھنؤ سے ہجرت کر کے کراچی آ چکے تھے۔ ان کے ساتھ’’نگار‘‘ بھی کراچی منتقل ہو گیا تھا۔ یہ ان کی زندگی کی شام تھی۔ جس آب و تاب اور گھن گرج کے ساتھ ’’نگار‘‘ لکھنؤ سے نکلا کرتا تھا، اسی طرح اب کراچی سے اس کا نکلنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ وہ خود اگر چہ اس کے مدیر اعلیٰ رہے لیکن اس کی ترتیب کی ذمّہ داری نیاز صاحب نے فرمان صاحب کو سونپ دی۔ رسالے پران کا نام بھی نائب مدیر کی حیثیت سے چھپنے لگا۔ ۱۹۶۲ تا۱۹۶۶ء فرمان صاحب’’نگارپاکستان‘‘ کو نیازؔ صاحب کی سرپرستی اور نگرانی میں ایڈٹ کرتے رہے لیکن ۲۴؍ مئی۱۹۶۶ء کو جب نیازؔ صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس رسالے کی تمام تر ذمہ ّ داری فرمانؔ صاحب کے کاندھوں پر آ پڑی اور وہی اس کے مدیر بھی بنے۔ نیازؔ فتح پوری کا نام اب بانی کی حیثیت سے چھپنے لگا۔ یہ روایت آج بھی قائم ہے۔
ڈاکٹر فرمان فتح پوری کو نیازؔ فتح پوری سے بے حد محبت و عقیدت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ’’نگار پاکستان‘‘ آج تک بند نہیں ہوا۔ وہ نیازؔ صاحب کے معتقد ہوتے ہوئے بھی ان کے مقلد کبھی نہیں رہے۔ انہوں نے ’’نگار پاکستان‘‘ کی ارادت سنبھالتے ہی اپنی راہ الگ نکالی۔ دھیرے دھیرے رسالے کو ایک نیا موڑ دیا اور اسے نئے جہات والبعاد سے روشناس کرایا۔ اب جب کہ فرمان صاحب کی ادارت میں اس رسالے کو نکلتے ہوئے۳۰ سال کا عرصہ بیت چکا ہے، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کا محاکمہ کیا جائے۔
یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ جب سے ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے ’’نگارِ پاکستان‘‘ کی ادارت سنبھالی، اسی وقت سے ان کی تصنیفی زندگی کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ ۱۹۶۲ء میں جب وہ اس سے منسلک ہوئے تو اس سال ان کی دو کتابیں ’’تدریس اردو‘‘ اور اردو رباعی کا فنی و تاریخی ارتقا‘‘ منظر عام پر آئیں۔ بعد کے دور میں ’’نگار پاکستان‘‘ نے ان کی تصنیفی زندگی کی راہ متعین کرنے اور ان کی علمی و ادبی سرگرمیوں کے فروغ میں بڑا مثبت کردار ادا کیا۔
’’نگارِ پاکستان‘‘ کی ترتیب کی ذمہ داری نبھانے کے دوسرے سال فرمانؔ صاحب نے اس کا نیازؔ فتح پوری نمبر(۱۹۶۳) دو جلدوں میں شائع کیا۔ جن لوگوں نے یہ نمبر دیکھا ہے وہ فرمان صاحب کی محنت و کاوش، دیدہ اور نیاز صاحب سے ان کی محنت عقیدت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ خاص نمبر نیازؔ فتح پوری کی حیات و شخصیت اور فکر و فن سے لے کر ان کی علمی و ادبی خدمات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں ان کی شاعری، افسانہ نگاری، مکتوب نگاری، مقالہ نگاری، تنقید، ناولٹ، نفسیات غرض کہ ہر پہلو کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ آخر میں نیازؔ صاحب کی تحریروں کا ایک جامع اشاریہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ نیازؔ فتح پوری پر تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے یہ نمبر آج بھی معلومات کا بے پناہ ذخیرہ ہے اور مستند حوالے کے طور پر کام میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ جب فرمان صاحب نے’’نگارِپاکستان‘‘ کا نیاز فتح پوری نمبر نکالنے کا ارادہ ظاہر کیا تونیاز صاحب نے اس کی سختی سے مخالفت کی اور انہیں ایسا کرنے سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن فرمان صاحب کی مستقل مزاجی دیکھ کر اور ان کے بار بار اصرار کرنے پر وہ بالآخر مان گئے۔ فرمان صاحب نے نہایت کم مدت میں ’’نیاز فتح پوری نمبر‘‘ دو جلدوں (مارچ اپریل۱۹۶۳ء اور مئی جون۱۹۶۳ء کے شمارے) میں ترتیب دیا۔ اور اس دور کے بہترین لکھنے والوں کی نگارشات شامل اشاعت کیں۔
اگلے سال یعنی۱۹۶۴ء میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے ’’نگار پاکستان‘‘ کا ایک اور خاص نمبر ’’تذکروں کا تذکرہ نمبر‘‘ کے نام سے شائع کیا ہے۔ یہ نمبر اردو شعراء کے تذکروں سے فرمان صاحب کی بے پناہ دلچسپی کا غماز ہے۔ اس خصوصی نمبر کی اشاعت کے بعد بھی تذکرہ یویسی کے فن سے ان کی دلچسپی قائم رہی، چنانچہ وہ اس موضوع پر مستقل غور خوض کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اسے اپنے ڈی۔ لٹ کے مقالے کا موضوع بنا لیا۔ یہ تحقیقی مقالہ ’’اردو شعراء کے تذکرے اور تذکرہ نگاری‘‘ کے عنوان سے ۱۹۷۲ء میں کتابی صورت میں شائع ہوا۔ فرمان صاحب کے اس تحقیقی کام کو اہل علم نے اس موضوع پرا ب تک سب سے’’دقیع اور جامع ‘‘کا قرار دیا۔ یہ اس امر کا بین ثبوت ہے ’’نگار پاکستان‘‘ کی ارادت ان کی تصنیفی زندگی میں کس طرح ممد و معاون رہی ہے۔
ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری ادارت میں شائع ہونے والے ’’نگار پاکستان‘‘ کے دو افسانہ اور افسانہ نمبر‘‘ (جنوری فروری۱۹۸۱ء) کا ذکر بھی بیجا نہ ہو گا جس کا پہلا اڈیشن چندہ ماہ میں ہیں ’’نایاب ‘‘ہو گیا۔ اس نمبر کی افادیت اور مقبولیت کے پیش نظر اسے فرمان صاحب نے ’’اردو افسانہ اور افسانہ نگار‘‘ کے عنوان سے کتابی صورت میں شائع کیا۔ اسی زمانے میں یہ کتاب بھارت میں بھی شائع ہوئی۔ اس کادوسرا بھارتی اڈیشن مکتبہ لمٹیڈ، نئی دہلی کے زیر اہتمام زیر طبع ہے۔ اس خاص نمبر(کتاب) کی ترتیب میں فرمان صاحب کو بڑی مشکلات کاسامنا کرنا پڑا۔ اردو فسانے کی اسّی سالہ تاریخ کی روشنی میں انہوں نے۲۵ نمائندہ افسانہ نگاروں کا انتخاب کیا۔ بڑی تلاش و تحقیق کے بعد ان کا پہلا افسانہ ڈھونڈا اور بتایا کہ یہ کس رسالے میں اور کب شائع ہوا۔ افسانے کے شروع میں ہر افسانہ نگار کا سوانحی خاکہ بھی پیش کیا نیز ان کی ادبی و تخلیقی سرگرمیوں کا بھر پور جائزہ لیا۔ کتاب کے شروع میں ایک مفصل باب اردو افسانے کی سمت و رفتار پر قلم بند کیا جس میں انہوں نے اردو افسانے کے چار ادوار قائم کیے، دورِ اول(۱۹۰۰ء اور دورِ چہار(۱۹۶۰ء)، دورِ دوم(۱۹۳۰ ء تا۱۹۴۷ء)، دورِ سوم(۱۹۴۷ء تا۱۹۶۰ء) دورِ چہارم(۱۹۶۰ء تا۱۹۸۰ء)۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ’’یہ ایک بڑا کا ہے جو تنقید بصیرت بھی چاہتا ہے‘‘۔
’’نگارِ پاکستان‘‘ کا ایک اور خاص نمبر’’ قمر زمانی نمبر‘‘ ہے جو ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی ادارت میں جنوری فروری۱۹۷۹ء میں شائع ہوا۔ یہ نمبر کتابی شکل میں ’’ قمر زمانی بیگم‘‘ کے نام سے اردو اکیڈمی سندھ کراچی سے اسی سال شائع ہوا۔ یہ نیاز فتح پوری کی ایک انوکھی داستانِ معاشقہ ہے اور بقول ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری ’’تاریخ ادب میں اپنی نوعیت کا پہلا رومان‘‘ اسے اگر فرمان صاحب کا تحقیقی کارنامہ کہا جائے تو بیجا نہ ہو گا۔ کیونکہ اس کتا ب میں انہوں نے بڑی تلاش و تحقیق کے بعد قمر زمانی بیگم کے حالات جمع کیے ہیں اور ان کی ادبی زندگی کا آغاز وپس منظر بیان کیا ہے اور وہ تمام خطوط سلسلہ وار ترتیب دیے ہیں جو قمر زمانی بیگم مدیر ’’نقاد‘‘ شاہ دلگیر کو اس صدی کی دوسری دہائی کے اور آخیر میں ایک عرصے تک لکھتی رہی تھیں۔ قمر زمانی بیگم اور شاہ دلگیر کے درمیان یہی خط و کتابت ایک عشقیہ داستان بن گئی۔ یہ داستان فرمانؔ صاحب نے اس کتاب میں بڑے دلچسپ اور انوکھے انداز میں بیان کی ہے۔ ساٹھ سال تک جو ایک رازِ سر بستہ تھا اورجس نے اردو کے بڑے بڑے ادیبوں کو چکر میں ڈال دیا تھا، ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے اس کا پردہ فاش کیا اور قمر زمانی بیگم کی اس طرح نقاب کشائی کی کہ لوگ ورطۂ حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے اس امر کا انکشاف کیا کہ قمر زمانی بیگم کے روپ میں یہ نیازؔ فتح پوری تھے جو شاہ دلگیر سے خط و کتابت کیا کرتے تھے اور شاہ دلگیر یہ سمجھتے رہتے تھے کہ کوئی خاتون (جن کا نام قمر زمانی ہے) ان سے مراسلت کر رہی ہیں، کہا جاتا ہے کہ شاہ دلگیر کو قمر زمانی کے عورت ہونے کا یقین ’’ایمانِ بالغیب‘‘ کی حد تک تھا بلکہ وہ قمر زمانی کے وجود کا اس طرح یقین رکھتے تھے جس طرح خود اپنے وجود کا۔ کتاب کی شانِ نزول کے بارے میں فرمان صاحب لکھتے ہیں :
’’قمر زمانی کے روپ میں نیاز فتح پوری کے یہی مکتوبات اور ان کے جواب میں دلگیر کے ہی خطوط اس وقت میرے سامنے ہیں اور قمر زمانی بیگم و شاہ دلگیر کی عشقیہ داستان کا مواد فراہم کرتے ہیں۔ یہ خطوط ادبی لحاظ سے حد درجہ دلچسپ ہیں اور بیشتر نیاز کی تخلیق ہونے کے سبب اردو ادب و صحافت کی تاریخ میں ایک نایاب اور انمول خزانے کچھ حیثیت رکھتے ہیں ‘‘ ۴؎
نیازؔ فتح پوری کو ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی مدبرانہ صلاحیتوں کا تین سال (۱۹۶۲ ء تا۱۹۶۵ء) کے اندر بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ان کے کام سے خوش تھے، انہیں بے حد عزیز رکھتے تھے اور دل سے دعائیں دیتے تھے۔ اس وقت مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے’’نگارِ پاکستان‘‘ کے پہلے صفحے پر نیازؔ فتح پوری کا نام چھپتا تھا۔ اسی صفحے پر ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا نام نائب مدیر کی حیثیت سے چھپتا تھا۔ اسی صفحے پر ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا نام نائب مدیر کی حیثیت سے چھپتا تھا۔ لیکن ہر ماہ ’’ملاحظات‘‘ کے نام سے اداریہ نیازؔ فتح پوری لکھتے تھے۔ (بہ استثنائے چند) مارچ۱۹۶۵ء کے ’’نگارِ پاکستان‘‘ میں انہوں نے ’’ملاحظات‘‘ کے تحت ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے بارے میں یہ عبارت رقم کی:
’’عزیزی فرمان فتح پوری نے جن کا نام نگار کے پہلے صفحے پر ہر ماہ آپ کی نگاہ سے گزرتا ہو گا اب ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کر لی ہے اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ اپنی تعلیم کاسلسلہ انہوں نے بالکل میری ہدایت کے مطابق قائم رکھا…میرے یہاں (کراچی) آنے کے بعد انہوں نے نگار کی بھی بڑی خدمات انجام دیں، چنانچہ نیاز نمبر کے دونوں حصوں کی ترتیب محض انہیں کی سعی و کوشش کا نتیجہ ہے اور سالنامہ تذکرہ نمبر تو خیر پورا انہیں کا مرتب کیا ہوا ہے۔ فرمان صاحب میرے ہم وطن ہیں، میرے عزیز ہیں، مجھ سے چھوٹے ہیں۔ اس لیے میری طرف سے اظہارِ تشکر کا تو کوئی موقع نہیں، دعا کا ضرور ہے، سواس کا تعلق بھی دل سے ہے، زبان سے نہیں ‘‘۔ ۵؎
ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری کی ادارت کے دوران کوئی بھی سال ایسا نہیں گزرا جب کہ ’’نگارِ پاکستان‘‘کا کوئی خاص نمبر نہ نکلا ہو۔ یہ بھی دراصل نیاز و نگار کی ہی ایک روایت کا تسلسل ہے۔ ’’نگار‘‘ کے خصوصی نمبروں یا سالناموں کا سلسلہ ۱۹۲۸ء میں مومنؔ نمبر کے اجراء سے شروع ہوتا ہے جو آج تک جاری ہے۔ خاص نمبروں کے موضوعات اور ان کی جامعیت سے فرمان صاحب کی ادب سے ہمہ گیر دلچسپی کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ زمانے کے سردو گرم کا مقابلہ کرتے ہوئے اتنی دلجمعی، مستقل مزاجی اور(commitment) کے ساتھ کسی رسالے کو ( وہ بھی ادبی) تیس سال تک پابندی سے ایڈٹ کرتے رہنا اور ہرسال اہتمام کے ساتھ اس کے خاص نمبر بھی نکالتے رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرمان صاحب کی ادارت میں گذشتہ تیس سال کے دوران شائع ہونے والے ’’نگارِ پاکستان‘‘ کے خاص نمبروں ۶؎ پر ایک نظر ڈالنا بے جا نہ ہو گا:
۱- نیاز فتح پوری نمبر۱؎ مارچ اپریل ۱۹۶۳ء
۲- نیاز فتح پوری ۲؎ مئی جون۱۹۶۳ء
۳- تذکروں کا تذکرہ نمبر مئی جون۱۹۶۴ء
۴- جدید تر شاعری نمبر جولائی اگست۱۹۶۵ء
۵- اصناف ادب نمبر دسمبر۱۹۶۶ء
۶- اصناف شاعری نمبر نومبر دسمبر۱۹۶۷ء
۷- مسائل ادب نمبر اکتوبر نومبر۱۹۶۸ء
۸- غالبؔ صدی نمبر جنوری فروری۱۹۶۷ء
۹- سرسید نمبر ۱؎ جنوری فروری۱۹۷۲ء
۱۰- میر انیس نمبر ستمبر اکتوبر۱۹۷۱ء
۱۱- سرسید نمبر ۲؎ جنوری فروری۱۹۷۲ء
۱۲- مولانا حسرت موہانی نمبر ۱؎ نومبر دسمبر۱۹۶۹ء
۱۳- مولانا حسرت موہانی نمبر ۲؎ اگست ستمبر۱۹۷۴ء
۱۴- ڈاکٹر محمود حسین نمبر جون جولائی۱۹۷۵ء
۱۵- قائد اعظمؒ نمبر اکتوبر نومبر۱۹۷۸ء
۱۶- علامہ اقبال نمبر جون جولائی۱۹۷۷ء
۱۷- مولانا محمد علی جوہر نمبر جنوری فروری۱۹۸۰ء
۲۰- افسانہ اور افسانہ نگار نمبر جنوری فروری۱۹۸۱ء
۲۱- فنِ تاریخ گوئی نمبر جنوری فروری۱۹۸۲ء
۲۲- خطباتِ محمود نمبر نومبر دسمبر۱۹۸۲ء
۲۳- جشنِ طلائی نمبر جنوری فروری۱۹۸۲ء
۲۴- نیاز صدی نمبر جنوری فروری۱۹۸۴ء
۲۵- فنِ عروض نمبر اپریل۱۹۸۵ء
۲۶- مکتوباتِ نیاز نمبر نومبر۱۹۸۵ء
۲۷- تنقید غزل نمبر نومبر۱۹۸۶ء
۲۸- غالبؔ بنگاہِ نیاز نمبر نومبر۱۹۸۷ء
۲۹- اردو شاعری کا فنی ارتقا نمبر دسمبر۱۹۸۸ء
۳۰- اردو نثر کا فنی ارتقا نمبر دسمبر۱۹۸۹ء
۳۱- اقبال بنگاہِ نیاز نمبر دسمبر۱۹۹۰ء
۳۲- نقدِ شعر نمبر دسمبر۹۹۱ء
۳۳- عورت فنونِ لطیفہ نمبر دسمبر۱۹۹۲ء
ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری کی ادارت و سرپرستی میں ’’نگارِ پاکستان‘‘لحظہ بہ لحظہ ترقی کا جانب گامزن ہے۔ اس کام میں انہیں امراؤ طارق جیسے معاون ملے ہیں جو ہر ہر قدم پر ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اگر چہ فتح پوری کے انتقال کو ۲۷ سال گزر چکے ہیں لیکن معنوی اعتبار سے ’’نگار‘‘ کا نیازؔ سے رشتہ ٹوٹا نہیں ہے۔ ’’نگارِ پاکستان‘‘ نیازؔ فتح پوری کے ہی ’’نگار‘‘ کا تسلسل ہے۔ یہ آج بھی ماہانہ شائع ہوتا ہے۔ ہرسال اب بھی اس کے خاص نمبر شائع ہوتے ہیں۔ آج بھی اس کے اداریے ’’ملاحظات‘‘ کے عنوان سے تحریر کیے جاتے ہیں۔ اس کے ہر شمارے پر بانی حیثیت سے علامہ نیازؔ فتح پوری کا نام درج ہوتا ہے اور پیشانی پر جاری شدہ۱۹۲۲ء لکھا ہوتا ہے۔ ’’نگارِ پاکستان‘‘ میں پہلے ہر طرح کے ادبی موضوعات پر مضامین شامل ہوتے تھے، لیکن گذشتہ چند ربرسوں کے شماروں سے پتہ چلتا ہے کہ فرمان صاحب نے ایک جدّت یہ پیدا کی ہے کہ اس کا ’’ہر شمارہ خصوصی شمارہ‘‘ بنا دیا ہے۔ اس کے تحت وہ کسی ایک موضوع پر بھر پور مواد پیش کرتے ہیں۔ اکثر کلاسیکی ادب کے نمونے اور ادبی نوادرات شائع کرتے ہیں، لیکن اس میں مستند اربابِ قلم کی نگارشات اور عصری تحریروں کو بھی جگہ دی جاتی ہے۔ بھارت میں شائع ہونے والے ادبی نمونے بالخصوص پیش کیے کہ ان تک رسائی پاکستان کے شائقین ادب کو بہت کم ہو پاتی ہے۔ یہ امتیاز شاید ہی اردو کے کسی اور رسالے کو حاصل ہو کہ اس کا ’’ہر شمارہ خصوصی شمارہ‘‘ قرار دیا جائے ’’نگارِ پاکستان‘‘ کے بعض ’’ہر شمارہ خصوصی شمارہ‘‘ کے مندر جات یہ ہیں :
۱- اردو ناول میں طنزو مزاح مارچ۱۹۸۸ء
۲- بہادر شاہ ظفرؔ اپریل۱۹۸۸ء
۳- کلیم الدین احمد کی خود نوشت مارچ۱۹۹۰ء
۴- ’’میری بہترین نظم‘‘ و مرتبہ محمد حسن عسکری اکتوبر۱۹۹۰ء
۵- اویس احمد ادیب کی تصنیف ولیؔ دکنی فروری۱۹۹۱ء
۶- غالبؔ کی فارسی غزل جنوری۱۹۹۱ء
۷- خیام کی رباعیات کا اولین ترجمہ جولائی۱۹۹۱ء
۸- جامعہ اردو ’’ادیب‘‘ کا جشن زرّیں نمبر اگست۱۹۹۱ء
۹- کتابیاتِ تحقیق نمبر ستمبر۱۹۹۱ء
۱۰- مشاطۂ سخن از صفدر مرزا پوری اپریل۱۹۹۲ء
۱۱- مولوی عبدالحق نمبر اگست۱۹۹۲ء
۱۲- ’’باغ و بہار‘‘ مرتبہ رشید حسن خاں اکتوبر۱۹۹۲ء
۱۳- بی امّاں اور بیگم حسرت موہانی نومبر۱۹۹۲ء
یہ ناممکن ہے کہ ’’نگارِ پاکستان‘‘ کا ذکر آئے اور ڈاکٹر فرمانؔ صاحب کے تحریر کردہ اداریوں جو وہ ’’ملاحظات‘‘ کے نام سے ہر ماہ لکھتے ہیں، کا ذکر نہ آئے۔ ’’ملاحظات‘‘ کے عنوان سے’’نگار/نگارِ پاکستان‘‘ کا اداریہ چالیس سے زیادہ عرصے تک لکھا۔ پاکستان آنے کے بعد بھی ’’ملاحظات‘‘ وہی لکھتے رہے۔ اور یہ سلسلہ ان کے انتقال سے چند ماہ قبل تک جاری رہا۔ انتقال سے چند ماہ قبل کے پرچوں اور درمیان کے بعض پرچوں ( مثلاً نیاز فتح پوری نمبر کے دونوں شماروں ) کے ملاحظات ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے تحریر کیے۔ نیازؔ فتح پوری کے ملاحظات اپنے اندر ایک مدیرانہ شان رکھتے تھے۔ اور ان کی دیگر تحریروں کی طرح ملاحظات بھی لوگ دلچسپی سے پڑھتے تھے۔ ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری، نیازؔ صاحب کے ملاحظات کے بار ے میں لکھتے ہیں :
’’نگارِ پاکستان‘‘ کا اداریہ ’’ملاحظات‘‘ وہ عموماً پر چہ پریس جاتے جاتے لکھتے تھے۔ ملاحظات کا موضوع شروع سے’’سیاست‘‘ رہا ہے۔ وہ پورے مہینے مختلف زبانوں کے اخبارو رسائل غور و خوض سے پڑھتے رہتے تھے اور عالمی یا ملکی سیاست کی کروٹوں کا پورا جائزہ لینے کے بعد ان پرا ظہار خیال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ’’نگار‘‘ کے علمی و ادبی مقالات پڑھنے والوں کا ایک خاص حلقہ بن گیا تھا وہاں ان کے ’’ملاحظات‘‘ کے شیدائی بھی سیکڑوں کی تعداد میں تھے۔ اور بعض تو صرف اسی اداریے کے لیے ’’نگار‘‘ پڑھتے تھے‘‘ ۲؎
جیسا کہ پہلے کہا چکا ہے کہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری، نیاز کے معتقد ضرور ہیں لیکن نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ملاحظات کے سلسلے میں بھی اپنی راہ الگ نکالی۔ اور کسی ایک موضوع یا مسئلے پر ملاحظات لکھنے کے بجائے وہ مختلف النوع موضوعات پر ملاحظات قلم بند کرنے لگے۔ ان کے بیشتر ملاحظات کا موضوع خود نیاز فتح پوری رہے ہیں۔ مثلاً مئی۱۹۶۶ء کے ’’نگارِ پاکستان‘‘ میں وہ ’’ملاحظات‘‘ کے تحت نیاز صاحب کی علالت پھر صحت یابی اور پھر علالت کا یا تفصیل ذکر کرتے ہیں جس سے ان کی زندگی کے آخری ایام پر روشنی پڑتی ہے۔ نیازؔ صاحب جانبر نہ ہوسکے اور۲۴ ؍ مئی۱۹۶۶ء کو ان کا انتقال ہو گیا جون۱۹۶۶ء کا ’’نگارِ پاکستان‘‘ کلیتہً ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی ادارت میں شائع ہوا۔ اس شمارے میں انہوں نے ’’حق مغفرت کر لے عجب آزاد مرد تھا‘‘ کے تحت ملاحظات قلم بند کیا جس میں نیاز صاحب کے انتقال سے اردو دنیا میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا اسے بڑے موثر انداز میں بیان کیا۔ اس کے ایک ایک لفظ سے نیاز صاحب سے ان کی محبت اور عقیدت ٹپکتی ہے۔ اسے ہم بجا طور پر ایک بہترین تعزیتی تحریر اور نثر کا ایک عمدہ نمونہ کہہ سکتے ہیں۔
ملاحظہ ہو:
۲۴؍مئی، منگل، ۴ بجے صبح، نیاز صاحب (جنہیں دنیا نیاز فتح پوری کے نام سے جانتی ہے) ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے…یوں سمجھ لیجئے کہ اردو کا وہ آفتاب، جس کی کرنوں سے علم و فکر کے ایک دو نہیں، صدہا پہلو روشن تھے، ڈوب گیا آزادی فکر اور بے لاگ اظہارِ خیال کی قندیلیں بجھ گئیں۔ اب ایوان اردو میں دور تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ سرسید، مولانا حالیؔ، محمد حسین آزادؔ، نذیر احمد اور شبلیؔ کے تجرد علمی اور فکر و فن کیا یاد تازہ رکھنے والا اب کوئی باقی نہ رہا۔ مولانا ابوالکلام آزادؔ اور مولوی عبدالحق پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے۔ نیازؔ فتح پوری کے نام سے اس ایوان کی ایک شمع دلیلِ سحر بنی ہوئی تھی سو وہ بھی خاموش ہو گئی…نیاز صاحبِ اپنی ذات سے ایک ادارہ، ایک مکتب فکر اور ایک تحریک تھے۔ ہر چند کہ وہ طبعاً عزلت پسند گوشہ گیر تھے، کم آمیز و کم سخن تھے، لیکن غالبؔ کے اس شعر کے ترجمان تھے ؎
ہے آدمی بجائے خود اک محشرِ خیال
ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو
وہ گذشتہ پینسٹھ سال سے مسلسل لکھ رہے ہیں اور ایسی انفرادیت کے ساتھ کہ ان کی کسی تحریر کو صرف مکرر کہنا مشکل ہے۔ صحافت، ادبی تنقید، انشائیہ، مکتوب نگاری، تاریخ اسلام، جمالیات، افسانہ، ناولٹ، تحقیق، علوم عقلیہ، مذہبیات، نفسیات، معلوماتِ عامہ سب پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے اور اپنے مخصوص اسلوب نگارش و طرز کی بدولت ایسا نقش چھوڑ گئے ہیں کہ اردو میں جب بھی یہ موضوعات ومسائل علمی و فنی انداز سے زیر بحث آئیں گے، علامہ مرحوم کا نام ضرور لیا جائے گا۔ ان کی یہی ہمہ جہتی ہمہ گیری انہیں بیسویں صدی کے دوسرے ادیبوں سے ممتاز کرتی ہے‘‘۔ ۸؎
جولائی، اگست اور ستمبر۱۹۶۶ء کے ملاحظات ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری نے ’’نیاز صاحب مرحوم اور کراچی‘‘ کے عنوان سے لکھے جن میں ان کی کراچی آمد، قیام اور دیگر کوائف تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ نیازؔ صاحب کی پہلی برسی(۱۹۶۷ء) کے موقع پر ’’نگارِ پاکستان‘‘ کا ایک شمارہ فرمان صاحب نے ان کے نام وقف کیا اور ملاحظات میں نیاز صاحب مرحوم کے تعلق سے دل کو چھو لینے والی باتیں لکھیں۔
جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری کے ملاحظات مختلف النوع موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں۔ چنانچہ سیروسیاھت بھی ان کے ملاحظات کا موضوع رہا ہے۔ فرمان صاحب نے۱۹۸۰ء میں بھارت کی سیر کی تھی۔ اور یہاں ایک ماہ چند روز قیام کیا تھا۔ اس سفر کے حالات اور تاثرات انہوں نے ’’نگارِ پاکستان‘‘ کے۱۹۸۱ء کے شماروں میں ملاحظات کے تحت ’’بھارت میں ایک مہینے تین دن‘‘ کے عنوان سے بالاقساط شائع کیے جن میں بھارت کے اہل علم و ادب سے ملاقاتوں، یہاں کی علمی و ادبی سرگرمیوں نیز شب و روز کی دیگر مصروفیتوں کا ذکر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اس سفر کے بعد انہیں ستمبر۱۹۸۱ء میں جموں و کشمیر کے سفر کا موقع ملا۔ چنانچہ واپسی پر انہوں نے ’’نگارِ پاکستان‘‘ کے دسمبر۱۹۸۱ء کے ملاحظات میں جموں و کشمیر کا سفر نامہ ’’خطہ بے نظیر و نظر گیر‘‘ جموں و کشمیر ‘‘ کے عنوان سے قلم بند کیا۔ اور اپنے تاثرات بڑے دل نشیں انداز میں بیان کیے۔ ان کی یہ دونوں تحریروں اردو کے بہترین سفرناموں میں جگہ پا سکتی ہیں۔
ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے جب سے ’’نگارِ پاکستان‘‘ کا ہر شمارہ خصوصی شمارہ قرار دیا ہے اس وقت سے وہ ملاحظات کے تحت رسالے میں شامل ادب پارے کے مصنف یا مرتب کا مختصر لیکن نہایت جامع تعارف پیش کرتے ہیں۔ اس کے تمام علمی و ادبی کارناموں اور اس کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو وہ ایک یادو پیراگراف میں نہایت حسنِ سلیقہ کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ نیز شامل اشاعت تخلیق کی اہمیت و افادیت کو بھی بخوبی واضح کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے ملاحظات میں شخصی کوائف نگاری، مرقع نگاری اور تذکرہ نگاری کے بڑے اچھے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ’’نگارِ پاکستان‘‘ کی ایک اشاعت میں انہوں نے کلیم الدین احمد کی خود نوشت’’ اپنی تلاش میں ‘‘ کو خصوصی موضوع بتایا، چنانچہ ملاحظات میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں :
’’کلیم الدین احمد ادو ادب کے ان بڑے ناقدروں میں ہیں جو ہزار اختلاف کے باوجود، اردو زبان و ادب کی تاریخی میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کی دو ابتدائی کتابوں ’’اردو شاعری پر ایک نظر‘‘ اور اردو تنقید پرا یک نظر‘‘ نے اردو ادب کے بحر منجمد میں وہی تلاطم و طوفان پیدا کیا جو کسی وقت مولانا حالیؔ نے ’’مقدمہ شعرو شاعری‘‘ کے ذریعہ پیدا کیا تھا۔ کلیم الدین احمد نے قدیم و جدید دونوں قسم کے ادب پر قلم اٹھایا ہے اور ہر جگہ اپنی انفرادیت کو برقرار رکھا ہے۔ تنقید کے ساتھ انہوں نے قدیم تذکروں اور دواوین کی ترتیب و تدوین، لغت نویسی اور خود نوشت کے عنوان سے بھی اردو کو بہت کچھ دیا ہے‘‘۔ ۹؎
ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری کے ملاحظات نہ صرف مرقع نگاری کے بڑے اچھے نمونے پیش کرتے ہیں بلکہ انتقادی پہلو بھی ان میں نمایاں ہوتا ہے، اس لیے تنقیدی نقطۂ نظر سے بھی ان کی بے حد اہمیت ہے۔ فرمان صاحب نے بعض ملاحظات میں ’’وفیا‘‘ کو بھی اپنا موضوع بنایا ہے جس میں وہ مرحوم کی نہ صرف خوبیاں بیان کرتے ہیں بلکہ اس سے اپنے ذاتی مراسم اور تعلقات کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کے اٹھ جانے سے انہیں جو دلی صدمہ پہنچا ہے اس کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ ایسی ہی ان کی ایک تحریر انجمؔ اعظمی مرحوم کے سلسلے میں ہے۔ وہ لکھتے ہیں :
’’انجمؔ اعظمی ایک اچھے استاد، نقاد اور شاعر تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ ایک بہت اچھے آدمی تھے۔ خوش اخلاق، با وضع، اور حد درجہ خود دار ان کی ذہانت، وسعت مطالعہ اور طرزِ گفتگو کے سب ہی قائل تھے اور گھائل تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ کہ وہ موضوعِ زیر بحث پر نہایت مدلل اور دو ٹوک گفتگو کرتے تھے اور ایسی خود اعتمادی اور دل آویزی کے ساتھ کہ اپنی بات، اپنے مخاطب سے بہر حال منوا لیتے تھے۔
نیاز یاد گاری خطبوں کے موقع پر، ہر سال ابتدائی تقریر وہی کیا کرتے تھے اور حق یہ ہے کہ اپنے دلکش انداز تخاطب سے سامعین کا دل موہ لیتے تھے۔ افسوس کہ ’’نیاز گاری لکچر کااسٹیج‘‘ انجم اعظمی کی آواز سے محروم ہے۔ مجھے ان کی یاد آج بُری طرح ستارہی ہے، کہاں ڈھونڈنے جاؤں، کہاں سے انہیں لاؤں اورجلسے کی پہلی تقریر ان سے کیسے کراؤں۔ وائے محرومی وائے مجبوری !‘‘ ۱۰؎
ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری کی صحافتی زندگی کا محور ’’نگارِ پاکستان‘‘ ہے۔ جوتسلسل ہے نیاز فتح پوری کے ’’نگار‘‘ (بعدہٗ ’’نگارِ پاکستان‘‘ ) کا۔ بلکہ ’’نگارِ پاکستان‘‘ انہیں کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے آج تک زندہ ہے۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ ’’نگارِ پاکستان‘‘ محض ایک رسالے کا نام نہیں، بلکہ اب یہ ایک ادارہ بن چکا ہے جسے ایک انجمن کہہ لیجے یا ’’حلقۂ نیاز و نگار‘‘ کا نام دیجیے۔ اس ادارے، انجمن یا حلقے کی جانب سے نیازؔ فتح پوری کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے۱۹۸۴ء سے سالانہ نیاز یاد گاری پر خطبے اور نیاز ایوارڈ کی بنا ڈالی گئی۔ اسی سال نیاز فتح پوری کا صد سالہ جشن ولادت ’’نیاز صدی‘‘ کے نام سے منایا گیا۔ اس سے ایک سال قبل یعنی۱۹۸۳ء میں ’’نگارِ پاکستان‘‘ کا جشنِ طلائی منایا گیاتھا۔ ان تمام سرگرمیوں کی روئدادیں، رپورٹیں اور تصویریں ’’نگارِ پاکستان‘‘ میں نہایت اہتمام کے ساتھ شائع کی گئیں۔ ۹۹۸۳ء میں جشن طلائی کے موقع پر نگارِ پاکستان کا ’’جشن طلائی نمبر‘‘ شائع کیا گیا۔ اسی طرح ۱۹۸۴ء میں نیاز صدی تقریبات کے موقع پر اس کے ’’نیاز صدی نمبر‘‘ اجرا عمل میں آیا۔ نیاز یادگاری خطبات کا جو سلسلہ دس سال قبل شروع کیا گیا تھا وہ آج بھی جاری ہے۔ اور اس کے جلسے ہر سال کراچی میں نہایت تزک و احتشام کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس میں بھارت اورپاکستان کے سرکردہ ادیبوں اور دانشوروں کو نیاز فتح پوری پر لکچر دینے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل رپورٹ ہر سال’’نگارِ پاکستان‘‘ کے صفحات کی زینت بنتی ہے۔ نیاز فتح پوری سے متعلق تمام یاد گاری خطبوں، علمی مذاکروں، ادبی اجلاسوں اور سرگرمیوں کے روحِ رواں ڈاکٹر فرمانؔ فتح پوری ہوتے ہیں۔ انہیں ان کاموں میں حلقۂ نیاز و نگار سے بڑی معاونت ملتی ہے اور حلقۂ نیاز و نگار کا ’’نگارِ پاکستان‘ کے بغیر تصور ناممکن ہے۔
اس امر کا ذکر بے جا نہ ہو گا کہ ’’نگارِ پاکستان‘‘ کی جڑیں اگر ماضی میں نیازؔ فتح پوری سے ملتی ہیں تو حال میں اس کا رشتہ فرمان فتح پوری سے استوار ہے ’’نگارِ پاکستان‘‘ کو یہ ہم ماضی سے الگ کر سکتے ہیں نہ حال سے جدا ماضی کے ’’نگار‘‘ کا تصور جس طرح نیاز فتح پوری کے بغیر نہیں کیا جا سکتا اسی طرح حال کے ’’نگارِ پاکستان‘‘ کے بارے میں فرمانؔ فتح پوری کے بغیر سوچنا امر محال ہے۔ ایک طرف ماضی ہے تو دوسری طرف حال، ایک طرف نیاز ہیں تو دوسری فرمانؔ۔ میں ’’نگارِپاکستان‘‘ کو قدیم و جدید، ماضی و حال اور نیاز و فرمان کے درمیان کی ایک کڑی تصور کرتا ہوں۔ اسی لیے میں ’’نیاز و نگار‘‘ کی ثنویت کا نہیں، بلکہ، نیاز و فرمان و نگار، کی تثلیث کا قائل ہوں !
٭٭
حواشی
۱- فرمانؔ فتح پوری، ملاحظات، ’’نگارِ پاکستان‘‘(کراچی) نیاز فتح پوری نمبر ( حصہ اول)، مارچ اپریل۱۹۶۳ء، ص۹-۱۰۔
۲- ’’نگار ‘‘ فروری ۱۹۲۲ء سے آگرہ ہی سے نکلنا شروع ہوا، لیکن ابو الخیر کشفی نے اپنے ایک مضمون میں نہ جانے یہ کیوں لکھ دیا کہ ’’نگار کا پہلا شمارہ فروری۱۹۲۲ء میں بھوپال سے شائع ہوا، اگر چہ اس کا تجارتی شعبہ آگرہ میں تھا‘‘(دیکھیے ابوالخیر کشفی کا مضمون ’’نگار اور اس کی روایات‘‘ مشمولۂ نگارِ پاکستان(کراچی) نیاز فتح پوری نمبر (حصہ دوم) مئی جون۱۹۶۳ء ص۵۴ ’’نگار‘‘ آگرہ ہی سے جاری ہوا۔ اس کے فروری ۱۹۲۲ء تادسمبر۱۹۲۲ء کے شمارے آگرہ ہی سے نکلے۔ جنوری۱۹۲۳ء میں یہ بھوپال منتقل ہو گیا۔ اس ضمن میں خود نیازؔ فتح پوری کی تحریر سند کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ اپنے ایک مضمون ’’والد مرحوم، مَیں اور ’’نگار‘‘ میں لکھتے ہیں :
’’غالباً نومبر۱۹۲۱ء کی بات ہے کہ لطیف الدین احمد (ل۔ احمد) کے مکان پر چند مخصوص احباب (ڈاکٹر ضیاء عباس ہاشمی، مخمورؔ اکبرآبادی، مالک حبیب احمد خاں، مقدس اکبرآبادی، شاہ دلگیر اکبرآبادی وغیرہ اور خود لطیف صاحب) کا اجتماع ہے اور ایک رسالہ جاری کرنے کی تجویز پر گفتگو ہوتی ہے( اس وقت ’’نقاد ‘‘ بند ہو چکا تھا) اور اس کا اجراء طے پا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسوال سامنے آتے ہیں۔ ایک نام کا، دوسرا سرمایہ کا۔ چوں کہ یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ میں اسے مرتب کروں گا اس لیے اڈیٹر کی زندگی کا کوئی سوال سامنے نہ تھا۔ رہا نام اس کے متعلق جب میری رائے طلب کی گئی تو میں نے ’’نگار‘‘ تجویز کیا…
اس کے بعد سرمایہ کا سوال سامنے آیا تو یہ طے پایا کہ فی الحال کم از کم بیس اصحاب بیس بیس روپے نگار فنڈ میں جمع کر دیں اور پہلا پرچہ آگرہ سے شائع ہو۔ اس کے بعد میں بھوپال آگیا اور پہلا پر چہ فروری۲۲ء مرتب کر کے آگرہ بھیج دیا اور مخمور و لطیف نے آگرہ پریس میں چھپوا کر شائع کیا… اور دسمبر۲۲ء تک نگار آگرہ ہی سے نکلتارہا‘‘(دیکھیے نیازؔ فتح پوری، ’’والد مرحوم، مَیں اور نگار‘‘ مشمولۂ ’’نگار پاکستان‘‘ (کراچی) نیاز فتح پوری نمبر(حصہ اول) مارچ اپریل ۱۹۶۳ء، ص۳۹-۴۰)
۳- مظفر علی سید نے ادبی موضوعات پر ’’نگار‘‘ کے جملہ خاص نمبروں کی کتابی شکل میں اشاعت پر زور دیا ہے۔ دیکھیے ان کا مضمون ’’نقدِ نیاز و نگار ‘‘مشمولۂ ارتقاء‘‘(کراچی) ارتقاء مطبوعات، اپریل ۱۹۹۰ء ص۱۰۳۔
۴- فرمانؔ فتح پوری (مرتب ’’قمر زمانی بیگم‘‘(کراچی)اردو اکیڈمی ۱۹۷۹) ص۲۲۔
۵- نیازؔ فتح پوری، ملاحظات ’’نگارِ پاکستان‘‘(کراچی)، مارچ۱۹۶۵ء ص، ۷-۸
۶- بہ حوالہ ’’نگار پاکستان‘‘ (کراچی) جنوری۱۹۹۳ء ص، ۷۵-۷۸۔
۷- فرمانؔ فتح پوری، ملاحظات(حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا) ’’نگارِ پاکستان‘‘(کراچی) جون۱۹۶۶ء ص۶
۸- ایضاً، ص۳
۹- فرمانؔ فتح پوری، ملاحظات، ’’نگارِ پاکستان‘‘(کراچی)، مارچ ۱۹۹۰ء ص۲
۱۰- فرمانؔ فتح پوری، ملاحظات ’’نگار پاکستان‘‘(کراچی) جنوری ۱۹۹۱ء، ص ۶
٭٭٭
شبلی کا تصورِ لفظ و معنیٰ
(’شعر العجم‘ کے حوالے سے)
شاعری کی حقیقت بیان کرتے ہوئے شبلیؔ نے ’شعر العجم‘ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ’’شاعری وجدانی اور ذوقی چیز ہے‘‘۔ شاعری کا دوسرانام انھوں نے ’’قوت احساس‘‘ بتایا ہے۔ یہاں انگریزی شاعر ولیم ورڈزورتھ (William Wordsworth) کی بیان کردہ شاعری کی تعریف ذہن میں آتی ہے جس میں انھوں نے یہ کہا تھا کہ:
"Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings”
آگے چل کر شبلیؔ لکھتے ہیں کہ جب یہی احساس الفاظ کا جامہ پہن لیتا ہے تو شعر بن جاتا ہے۔ گویا شبلیؔ کے نزدیک لفظ کی حیثیت ہئیت (Form)کی ہے اور اس کا موضوع (Content) وہ احساس ہے جو شاعری سے عبارت ہے۔ ورزڈورتھ نے چیز کو "Powerful feelings”کہا ہے۔ شبلیؔ اسے ’’قوی جذبہ‘‘ کہتے ہیں اور "Spontaneous”کے لیے وہ ’’بے ساختہ‘‘ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ شعر کی مکمل تعریف شبلیؔ یوں بیان کرتے ہیں :
’’جب اس پر (انسان پر) کوئی قومی جذبہ طاری ہوتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے موزوں الفاظ نکلتے ہیں ‘ اسی کا نام شعر ہے۔ ‘‘(۱)
یہاں ’’موزوں الفاظ‘‘ شبلیؔ کا اضافہ ہے ورنہ ورڈزورتھ کی شعر کی تعریف میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ لیکن منطقی پیرایے میں شعر کی تعریف بیان کرتے ہوئے شبلیؔ لکھتے ہیں کہ جو جذبات الفاظ کے ذریعہ سے ادا ہوں وہ شعر ہے، اور چوں کہ یہ الفاظ سامعین کے جذبات پر بھی اثر کرتے ہیں، یعنی سننے والوں پر بھی وہی اثر طاری ہوتا ہے جو صاحبِ جذبہ کے دل پر طاری ہوتا ہے، اس لیے شعر کی تعریف وہ یوں بھی کرتے ہیں کہ ’’جو کلام انسان جذبات کو برانگیختہ کرے اور ان کو تحریک میں لائے وہ شعر ہے۔ ‘‘
شبلیؔ شعر کی تعریف بیان کرتے وقت لفظ کے Conceptualیا Denotative معنی مراد نہیں لیتے، یعنی وہ لفظ کی لغوی حیثیت کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے EmotiveاورExpressive معنی مراد لیتے ہیں۔ ہر لفظ اپنا کوئی نہ کوئی مفہوم (Sense) یا Conceptرکھتا ہے جسے Conceptual meaning کہتے ہیں۔ اسی کو Denotative meaningبھی کہتے ہیں کیوں کہ اس سے لفظ کے لغوی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ شبلیؔ نے شعر کی جو تعریف بیان کی ہے اس میں لفظ کے نہ تو انھوں نے اس کے Conceptual معنی میں استعمال کیا ہے اور نہ ہی Dentative معنی میں۔ زبان کا بنیادی کام ابلاغ یا ترسیل معنی اور ادائے مطلب ہے۔ متکلم سے سامع تک زبان پیغام رسانی یا ترسیل (Communication)کا جو فریضہ انجام دیتی ہے یا روز مرہ کے معمولات میں زبان سے افہام و تفہیم کا جو کام لیا جاتا ہے وہ الفاظ کے Conceptualیا Denotativeمعنی کے ذریعہ سے ہی ممکن ہوتا ہے لیکن شاعری کا کام الفاظ کے ذریعہ محض پیغام رسانی یا اطلاع یعنی (Information) بہم پہنچانا نہیں ہے بلکہ جیسا کہ شبلیؔ نے کہا ہے جذبات کو ’’برانگیختہ‘‘ کرنا ہے، اس لیے شعر میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں گے ان کا مقصد Emotive اور Expressiveیعنی جذبے کی ترسیل اور اظہار ہو گا نہ کہ اطلاع رسانی۔ لہٰذا جب شبلیؔ یہ کہتے ہیں کہ ’’جذبات الفاظ کے ذریعے ادا ہوں وہ شعرہے‘‘ تو وہ الفاظ سے یہاں ان کے Expressiveاور Emotiveمعنی ہی مراد لیتے ہیں۔
لفظ و معنی کے تصور سے وابستہ ایک دوسرا اہم پہلو وہ ہے جس میں شبلیؔ نے الفاظ کی صوت نقلی (Onomatopoeic) خصوصیت اور صوتی رمزیت (Sound symbolism) پر زور دیا ہے۔ جہاں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ محاکات کی تکمیل کن کن چیزوں سے ہوتی ہے، وہاں وہ اظہار کے لہجے اور آواز کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ ’’درد، غم، جوش، جذبہ، غیض، غضب ہر ایک کے اظہار کا لہجہ اور آواز مختلف ہے۔ اس لیے جس جذبہ کی محاکات مقصود ہو، شعر کا وزن بھی اسی کے مناسب ہونا چاہئے تاکہ اس جذبہ کی پوری حالت ادا ہوسکے۔ ‘‘ شبلیؔ آوازوں کو پست، بلند، شیریں، کرخت اور سریلی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آوازوں کے اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے جائیں جوان خصوصیت پر دلالت کرتے ہوں۔ اس سلسلے میں شبلیؔ نے انگریزی شاعر رابرٹ سدے (Robert Southey)کی ایک نظم کا حوالہ دیا ہے جس میں سیلاب کا ذکر ہے۔ شبلیؔ لکھتے ہیں کہ ’’ اس نظم میں تمام الفاظ اس قسم کے آئے ہیں کہ پانی کے بہنے، گرنے، پھیلنے، بڑھنے (وغیرہ، وغیرہ ) کے وقت جو آوازیں پیدا ہوتی ہیں، الفاظ کے لہجے سے ان کا اظہار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص خوش ادائی سے اس نظم کو پڑھے تو سننے والے کو معلوم ہو گا کہ زور شور سے سیلاب آ رہا ہے۔ ‘‘ شبلیؔ نے صورت و معنی کی مطابقت کی یہ ایک بہترین مثال پیش کی ہے۔ اسی کو صوتی رمزیت یا صوتی علامتیت (Sound symbolism) کہتے ہیں۔ جدید اسلوبیات نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ لسانیات کی صوتی سطح پر اسلوبیاتی تجزیے کا تمام تر کام صوتی رمزیت (Sound symbolism) ہی ہر مبنی ہے۔ شبلی غالباً پہلے اُردو نقاد ہیں جنھوں نے صوت و معنی (Sound and Sense) کے رشتے پر شاعری کے حوالے سے توجہ مرکوز ہے۔ (۲)
شبلی ایک صاحبِ اسلوب ہونے کے علاوہ اسلوب شناس بھی تھے۔ انھوں نے صوتی رمزیت کے اس نکتے کو واضح کرنے کے لیے مرثیے کا ایک بند بھی پیش کیا ہے جس میں اہلِ بیت، حضرت عباس اور ان کے گھوڑے پر پابندی بند کر دیے جانے کا ذکر ہے مرثیے کے اس بند کے ابتدائی چار مصرعے ’’د‘‘ (دال) پر ختم ہوتے ہیں جو ایک بندشی آواز یعنی Stop sound ہے جس کی ادائیگی میں ہوا کا اخراج نوک زبان کے سہارے مسوڑھوں پر رک جاتا ہے۔ اس بندے کے مفہوم کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو بندشی آواز ’’د‘‘ (دال) میں صوت و معنی کی جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے وہ بخوبی واضح ہو جائے گی۔ شبلیؔ نے صوت کے اس امتزاج کو پہچان لیا تھا۔ چنانچہ مرثیے کے اس بند کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اصل، نیچرل اور فطری حالت کا بیان ہے۔ وہ بند آپ بھی ملاحظہ فرمائیں :
دو دن سے بے زباں پہ جو تھا آب و دانہ بند
دریا کو ہنہنا کے لگا دیکھنے سمند
ہر بار کانپتا تھا سمٹتا تھا بند بند
چمکارتے تھے حضرتِ عباسِ ارجمند
تڑپاتا تھا جگر کو جو شور آبشار کا
گردن پھرا کے دیکھتا تھا منہ سوار کا
شبلیؔ نے ’شعر العجم‘ میں حسنِ الفاظ سے بھی تفصیل سے بحث کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اہلِ فن کے دو گروہ بن گئے ہیں، ایک لفظ کو ترجیح دیتا ہے اور دوسرا موضوع اور معنی کو۔ انھوں نے ’کتاب العمدہ‘ کے ایک باب ’’فی اللفظ والمعنی‘‘ کا ایک اقتباس بھی نقل کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ’’لفظ جسم ہے اور مضمون روح ہے، دونوں کا ارتباط ایسا ہے جیسا روح اور جسم کا ارتباط کہ وہ کمزور ہو گا تو یہ بھی کمزور ہو گی، پس اگر معنی میں نقص نہ ہو اور لفظ میں ہو تو شعر میں عیب سمجھا جائے گا۔ ۔ ۔ اسی طرح اگر لفظ اچھے ہوں لیکن مضمون اچھا نہ ہو تب بھی شعر خراب ہو گا اور مضمون کی خرابی الفاظ پر بھی اثر کرے گی۔ اسی طرح مضمون گو اچھا ہو لیکن الفاظ اگر بُرے ہیں تب بھی شعربے کار ہو گا۔ کیوں کہ روح بغیر جسم کے پائی نہیں جا سکتی۔ ‘‘
شبلیؔ کا خیال یہ ہے کہ زیادہ تر اہلِ فن لفظ کو مضمون پر ترجیح دیتے ہیں، کیوں کہ مضمون تو سب ہی پیدا کر سکتے ہیں لیکن شاعری کا کمال یہ ہے کہ مضمون ادا کن الفاظ میں کیا گیا ہے اور بندش کیسی ہے۔ خود شبلیؔ کا عقیدہ یہ ہے کہ شاعری یا انشا پردازی کا دارومدار زیادہ تر الفاظ ہی پر ہے۔ وہ ’گلستانِ سعدی‘ کی مثال دے کر یہ بتاتے ہیں کہ اس میں جو مضامین اور خیالات بیان کیے گیے ہیں وہ اتنے اچھوتے اور نادر نہیں ہیں، لیکن الفاظ کی فصاحت، ترتیب اور تناسب نے ان میں سحر پیدا کر دیا ہے۔ شبلیؔ لکھتے ہیں کہ ’’اگر انھیں مضامین اور خیالات کو معمولی الفاظ میں ادا کیا جائے تو سارا اثر جاتا رہے گا۔ ‘‘ وہ ظہوری کے ’’ساقی نامہ‘‘ کے مقابلے میں ’’سکندر نامہ‘‘ کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں الفاظ کی متانت، شان و شوکت اور بندش کی پختگی پائی جاتی ہے جو ساقی نامہ میں مفقود ہے۔ ’ ساقی نامہ‘ میں نازک خیالی، موشگافی اور مضمون بندی ضرور پائی جاتی ہے، پھر بھی شبلیؔ کے نزدیک ’سکندر نامہ‘ کا ایک شعر پورے ’ساقی نامہ‘ پر بھاری ہے۔ شبلیؔ کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ شاعر کو صرف الفاظ سے غرض رکھنی چاہیے اور معنی سے بالکل بے پروا ہو جانا چاہیے، بلکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مضمون خواہ کتنا ہی بلند اور نازک کیوں نہ ہو، لیکن اگر الفاظ مناسب نہیں ہیں تو شعر میں کچھ تاثیر پیدا نہ ہوسکے گی۔ شبلیؔ نے ’شعر العجم‘ میں یہ برملا کہا ہے کہ ’’ جن بڑے شعراء کی نسبت کہا جاتا ہے کہ ان کے کلام میں خامی ہے اس کی زیادہ تر وجہ یہی ہے کہ ان کے ہاں الفاظ کی متانت، وقار اور بندش کی درستی میں نقص پایا جاتا ہے ‘‘۔
شبلیؔ کے تصورِ لفظ و معنی کو سمجھنے کے بعد ہمیں ان کے تصورِ اسلوب کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ متبادل الفاظ، تراکیب اور فقروں کے درمیان بہتر انتخاب کو وہ بہتر اسلوب تصور کرتے ہیں۔ شبلیؔ نے ’شعرالعجم‘ میں جو بات آج سے بہت پہلے کہی تھی وہی بات عصر حاضر کے ایک معروف نقاد اور ماہر اسلوبیات نلزایرک انسکوسٹ( Nils Eriuk Enkvist)نے ان الفاظ میں کہی ہے:
"Style as the choice between alternative expressions”
(۳)
شبلیؔ متبادل الفاظ و تراکیب کے درمیان انتخاب کی مثال ان دو مصرعوں سے پیش کرتے ہیں :
ع تھا بلبلِ خوش گو کہ چہکتا تھا چمن میں
ع بلبل چہک رہا ہے ریاض رسولؐ میں
شبلیؔ لکھتے ہیں کہ ان میں مضمون بلکہ الفاظ تک مشترک ہیں پھر بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔
شبلیؔ نے میر انیسؔ، مرزا دبیر، مرزا ضمیر اور اردو اور فارسی کے دوسرے شعرا سے ایسی بے شمار مثالیں پیش کی ہیں جن کے دو بندوں یا اشعار میں معنی بالکل مشترک ہیں لیکن الفاظ کے انتخاب یا بقولِ شبلیؔ الفاظ کے ’’ادل بدل اور اُلٹ پلٹ‘‘ نے کلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ مرزا دبیرؔ اور میرانیسؔ کے کلام سے دو دو مثالیں ملاحظہ ہوں :
مرزا دبیرؔ
کس نے نہ دی انگوٹھی رکوع وسجود میں
جیسے مکاں سے زلزلے میں صاحبِ مکاں
میرانیسؔ
سائل کو کس نے دی ہے انگوٹھی نماز میں
جیسے کوئی بھونچال میں گھر چھوڑ کے بھاگے
شبلیؔ نے ’’ شعر العجم‘‘ میں فصاحت اور بلاغت سے متعلق بھی اپنی بیش قیمت آراء کا اظہار کیا ہے لیکن بادی النظر میں دیکھا جائے تو فصاحت و بلاغت کا مسئلہ دراصل تشکیلِ اسلوب کا مسئلہ ہے اور اس سلسلے کی بیشتر نظری بحثیں اسلوبیات (Stylistics) کے دائرے میں آتی ہیں۔ آج جدید لسانیات اور اسلوبیا ت کی روشنی میں اسلوب کی توضیح و تجزیے کا جو کام جاری ہے اس کی جڑیں بلاشبہ ’شعر العجم‘ میں تلاش کی جا سکتی ہیں۔
٭٭٭
غالبؔ – ؔ ایک سادہ بیان شاعر
اردو شعرا میں جو مقبولیت مرزا اسد اللہ خاں غالبؔ کے کلام کو حاصل ہوئی وہ بہت کم شاعروں کے حصے میں آئی، لیکن عام طور پر غالب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اردو کے ایک مشکل پسند شاعر تھے، ان کی شاعری فارسی شاعری کی مبینہ تقلید ہے، ان کے اشعار بے معنی ہیں یا یہ کہ ان کی شاعری میں جا بجا ابہام پایا جاتا ہے۔ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ غالب کی تشبیہیں نامانوس اور استعارے و تراکیب دور از کار ہیں، ان کے خیال میں پیچیدگی اور طرزِ بیان میں الجھاؤ پایا جاتا ہے۔ مزید برآں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ غالب کے یہاں گہرا فلسفہ پایا جاتا ہے جو عام انسانوں کی فہم و ذکا سے بالا تر ہے۔ غالب کے بارے میں حکیم آغا جان عیش نے تو یہ تک کہہ دیا تھا ؎
کلامِ میرؔ سمجھے اور زبانِ میرزا سمجھے
مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے
ان تمام باتوں کے با وصف غالبؔ کی بے پناہ مقبولیت اور شہرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ غالب آج بھی اتنے ہی مقبول شاعر ہیں جتنے کہ وہ اپنے دور میں تھے بلکہ رفتارِ زمانہ کے ساتھ ساتھ غالبؔ کی شہرت اور مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ آج غالبؔ کی ہمہ گیری و آفاقیت کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف ہندو پاک بلکہ دنیا کے تقریباً ہر بڑے ملک کے لوگ غالبؔ کے نام سے واقف ہو چکے ہیں۔ دنیا کے تمام بڑے شاعروں کی اگر کوئی فہرست مرتب کی جائے تو اس میں اردو کی جانب سے غالب کا نام ضرور شامل ہو گا۔ اس کے علاوہ غالبؔ کی شاعری اور ان کی زندگی پر حالیؔ سے لے کراب تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور جتنے مضامین شائع ہوئے ہیں اتنے شاید کسی دوسرے شاعر پر نہیں لکھے گئے۔ غالب کے اردو دیوان کو بھی بہتر سے بہتر طور پر شائع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کی زندگی سے لے کر اب تک دیوانِ غالبؔ کے بے شمار ایڈیشن منظرِ عام پر آ چکے ہیں اور دنیا کی بیشتر ترقی یافتہ زبانوں میں غالبؔ کے کلام کے ترجمے ہو چکے ہیں۔
غالبؔ کو جو لوگ مشکل پسند بتاتے ہیں انھیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک مشکل پسند شاعر عوام میں کیوں کر اتنا مقبول ہوسکتا ہے اور ہر آنے والی نسل ان کے کلام پر کیوں کر اپنا سردھن سکتی ہے۔ غالب کے بارے میں مختلف قسم کی رایوں سے قطعِ نظر اگر ان کی شاعری کا ذرا بغور مطالعہ کیا جائے اور ان کے کلام کو ایسے اشعار سے ہٹ کر دیکھا جائے جن میں الفاظ کی بازی گری اور تخیل کی اونچی اڑان پائی جاتی ہے تو ان کی شاعری پر سے مشکل پسندی، ابہام اور پیچیدگی کے پردے ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مشکل پسندی کی جگہ سادہ بیانی اور پیچیدگی اور الجھاؤ کی جگہ سلجھاہوا انداز نظر آنے لگے گا۔ غالبؔ کی شاعری کا یہی وہ پہلو ہے جس میں ان کی مقبولیت کا راز پوشیدہ ہے۔ اگر وہ مشکل پسند شاعر ہوتے اور ان کی شاعری بے معنی اور مہمل ہوتی تو زمانہ آج انھیں سرآنکھوں پر جگہ نہ دیتا اور نہ ہی ان کے دیوان کو ’’الہامی کتاب‘‘ کا درجہ دیا جاتا، اور محمد حسین آزادؔ بھی دیوانِ غالب کے بارے میں یہ نہ کہتے:
’’وہ یہی دیوان ہے کہ آج ہم عینک کی طرح آنکھوں سے لگائے پھرتے ہیں۔ ‘‘
غالبؔ کی پیچیدگی اور مشکل پسندی پر اردو میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور آئندہ بھی لکھا جائے گا، لیکن غالبؔ کی سہل پسندی اور سادہ بیانی کی طرف تنقید نگاروں کی بہت کم توجہ مبذول ہوئی ہے۔ حالانکہ ان کے یہاں صاف، سادہ، سلیس اورسلجھے ہوئے اشعار کی کوئی کمی نہیں۔ اس طرح کے اشعار ہمیں ان کے دیوان میں جا بجا ملتے ہیں، مثلاً :
دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز
پھر ترا وقتِ سفر یاد آیا
________
جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن
بیٹھے رہیں تصورِ جاناں کیے ہوئے
________
مہرباں ہوکے بلا لو مجھے چاہو جس دم
میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں
________
ہم کو ان سے وفا کی ہے امید
جو نہیں جانتے وفا کیا ہے
________
مجھ کو دیارِ غیر میں مارا وطن سے دور
رکھ لی مرے خدا نے مری بیکسی کی لاج
________
نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں
تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں
غالبؔ دہلی کے رہنے والے تھے مگر ان کی پیدائش آگرے میں ہوئی تھی۔ یہ وہی دہلی ہے جو کئی بار گردشِ زمانہ کے ہاتھوں اُجڑ چکی تھی اور جس کی ساری زیب و زینت اور آرائش خاک میں مل چکی تھی۔ غالبؔ کا اپنا دور بھی کسی پُر آشوب دور سے کم نہ تھا۔ غدر کے خوں چکاں واقعات ان کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے تھے۔ دہلی کی رونق کو مٹتے ہوئے اور سلطنتِ مغلیہ کے چراغ کو گل ہوتے ہوئے انھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کس مپرسی اور بدحالی کی وجہ سے دہلی کے رہنے والوں میں وہ بانکپن نہیں رہ گیا تھا جو لکھنؤ میں پایا جاتا تھا۔ دہلی والوں کی طرزِ معاشرت میں بے پناہ سادگی پیدا ہو چکی تھی۔ تکلف و تصنع اور زیبائش و آرائش تو نام کو بھی باقی نہ تھی۔ دراصل یہ کیفیت غالبؔ کے عہد سے بہت پہلے ہی پیدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ میر تقی میرؔ جب دہلی کی بدحالی سے گھبرا کر لکھنؤ پہنچے تھے تو وہاں کے طرحداروں اور بانکوں نے ان کی سادگی پر خوب خوب قہقہے بلند کیے تھے۔ غالبؔ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں وہ ماحول بھی امیرانہ نہ تھا۔ والد کا انتقال ان کی کم عمری ہی میں ہو چکا تھا۔ جب یہ بڑے ہوئے تو انھیں طرح طرح کی معاشی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ غرض یہ کہ ان سب باتوں نے غالبؔ کو ایک سادہ انسان بن کر رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن زمانے کی صعوبتوں کو دیکھ کر بلکہ جھیل کر نہ تو وہ میرؔ کی طرح سنجیدہ ہوئے اور نہ ہی انھوں نے یاس کا کوئی عنصر قبول کیا۔ غالبؔ کی زندگی میں جو سادگی پیدا ہوئی تھی اس کا اثر ان کی شاعری پر بھی پڑا اور ان کی شاعری ’’سادگی و پرُکاری ‘‘ کا ایک نمونہ بن گئی۔
غالبؔ کی شاعری کو تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور شعر کہنے کی عمر سے لے کر پچیس برس کی عمر تک کا ہے۔ دوسرا دور پچیس برس کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور قلعۂ معلّیٰ کی ملازمت تک جاری رہتا ہے۔ ان کی شاعری کے تیسرے دور کو قلعۂ معلی کی ملازمت سے لے کر آخرِ عمر تک خیال کیا جاتا ہے۔ پہلے اور دوسرے دور میں غالب فارسی سے بہت قریب نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری میں مرزا بیدلؔ کی برملا تقلید پائی جاتی ہے۔ لیکن تیسر ا دور جو قلعۂ معلی کی زندگی سے وابستہ ہے، وہی ان کی شاعری کا اہم ترین زمانہ ہے۔ اس دور میں ان کی شاعرانہ خوبیاں انتہائی عروج پر نظر آتی ہیں۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ سمجھ گئے تھے کہ کامیاب غزل گو بننے کے لیے سہل پسندی کا ہی راستہ اختیار کرنا ہو گا۔ چنانچہ ان کا اس دور کا کلام ندرتِ خیال، شگفتگیِ بیان اور لطافتِ زبان کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بڑی سادگی بھی رکھتا ہے۔ دراصل ان کی اسی شاعری نے انھیں اردو شعرا کی صفِ اول میں لا کھڑا کیا۔
اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک شاعر، دوسرے شاعر کے کلام سے اثر قبول کرتا ہے، لیکن غالب ایک ایسے شاعر ہیں جنھوں نے اپنی تحریروں سے آپ اثر قبول کیا ہے۔ شاعری کے ابتدائی دور میں وہ مرزا بیدلؔ سے ضرور متاثر تھے، لیکن یہ اثر صرف ان کی جوانی تک قائم رہا اور رفتہ رفتہ بیدلؔ کی تقلید کم ہوتی گئی۔ فارسی کا جنون جب ان کے ذہن و دماغ سے جاتا رہا تو انھوں نے اردو مکتوب نگاری کی بنیاد ڈالی اور اردو میں ایسے سادہ اورسلیس خطوط لکھے کہ نہ تو ان سے پہلے کوئی ایسے خط لکھ سکا اور نہ ان کے بعد ہی کسی کو اس اسلوب میں خط لکھنے کی جرأت ہوئی۔ اس سے قبل فارسی شاعری کی طرح غالب خطوط بھی فارسی ہی میں لکھا کرتے تھے۔ زبان کی اس تبدیلی کا ان کی شاعری پر بہت گہرا اثر پڑا اور یہ تبدیلی ایک طرح سے اردو شاعری کے لیے فالِ نیک ثابت ہوئی۔ چنانچہ یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ غالب اگر خطوط اردو میں نہ لکھتے تو غالباً ان کی اردو شاعری بھی اتنی سادگی اور سہل پسندی کی حامل نہ ہوتی۔ غالب کو دہلی کی عام بول چال کی زبان بہت پسند تھی، چنانچہ ان کے خطوط کی زبان بھی وہی ہے جواس عہد کی دہلی کی زبان تھی کہ ان کو یہی زبان عزیز تھی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میر امّن کی ’باغ و بہار‘ کو مرزا رجب علی بیگ سرورؔ کی ’فسانۂ عجائب‘ پر غالب نے ہمیشہ فوقیت دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ’باغ و بہار‘ دہلی کی صاف، ستھری اور سلجھی ہوئی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس کے برخلاف ’فسانہ عجائب‘ پرتصنع اور مقفیٰ ومسجّع نثر کا ایک نمونہ بن کر رہ گئی جسے غالب نے ’’بھٹیار خانہ‘‘ کہا ہے۔ اگر غالب پُر تکلف اندازِ بیان، پر تصنع اسلوب اور عبارت آرائی کے شیدائی ہوتے تو ’فسانہ عجائب‘ کی زبان کو خوب سراہتے اور اس کی چاشنی اور رنگینی سے خوب لطف اندوز ہوتے، لیکن ان کے مزاج میں سادگی کا عنصر بدرجۂ اتم موجود تھا۔ انھوں نے مشکل اور پر تکلف اندازِ بیان کونہ تو خود پسند کیا اور نہ دوسروں ہی کے لیے اسے بہتر سمجھا۔
ان سب باتوں سے قطعِ نظر، جس چیز نے غالب کو سہل پسندی اور سادہ بیانی کی طرف مائل کیا وہ تھا ان کا وہ احساس جو اس دور کے عوام کی ناسخن فہمی یا کم سخن شناسی کے سبب پیدا ہوا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح کی شاعری وہ کر رہے ہیں، وہ عوام کے مذاق اور ان کی فہم سے بالاتر ہے۔ عوام کا معیار اتنا بلند نہیں کہ وہ تخیل کی بلند پروازیوں کو سمجھ سکیں۔ اس جھنجلا ہٹ کا اظہار ان کی شاعری میں کہیں کہیں پایا جاتا ہے، مثلاً :
ہوں گرمیِ نشاطِ تصور سے نغمہ سنج
میں عندلیبِ گلشنِ ناآفریدہ ہوں
________
نہ ستائش کی تمنّا نہ صلے کی پروا
گر نہیں ہیں مرے اشعار میں معنی نہ سہی
لیکن آخری دور میں جب غالب کو عوام نے ان کے اشعار کی سادگی اور صفائی کی وجہ سے سر آنکھوں پر بٹھانا شروع کر دیا تو وہ فخر یہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے ؎
ہیں اور بھی دنیا میں سخن ور بہت اچھے
کہتے ہیں کہ غالبؔ کا ہے اندازِ بیاں اور
غالب کی شاعری پر مشکل پسندی، پیچیدگی اور مبہم ہونے کے جو الزامات عائد کیے گئے ہیں ان میں غالب یا ان کی شاعری کا کوئی قصور نہیں، قصور اس بات کا ہے کہ عوام نے اپنے فیصلے میں بہت جلد بازی سے کام لیا اور بغیر سوچے سمجھے ان کی شاعری کو ’’بے معنی‘‘ کہہ ڈالا۔
غالب سے پہلے ہمیں اردو میں ایسے متعدد شعرا نظر آتے ہیں جو اشعار کی سادگی اور سلاست میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جو بات غالب کے یہاں ہے وہ دوسرے شعرا کے یہاں نہیں پیدا ہوسکی۔ اس سلسلے میں میرتقی میرؔ کا نام پیش کیا جا سکتا ہے۔ میر کے یہاں سادہ، سلیس اور عام فہم اشعار کی تعداد کافی ہے اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اردو کے ایک سادہ بیان اور عام لب و لہجے کے شاعر ہیں، اور انھوں نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ انھیں ’’گفتگو عوام سے ہے‘‘، لیکن غالب کے سلسلے میں جو تعصب ہمارے ذہن کے اندر جاگزیں ہو چکا ہے اس سے قطعِ نظر کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو غالب کے کلام میں بھی میرؔ جیسی سادگی کی مثالیں جا بجا ملیں گی۔ میرؔ کا ایک شعر ہے ؎
بھاگے مری صورت سے وہ عاشق میں اس کی شکل پر
میں اس کا خواہاں یاں تلک وہ مجھ سے بیزار اس قدر
غالب نے اسی خیال کو کتنے سادہ، سہل اور برجستہ انداز میں یوں پیش کیا ہے ؎
ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار
یا الٰہی یہ ماجرا کیا ہے
میرؔ کا شعر ہے ؎
سراہا اُن نے ترا ہاتھ، جن نے دیکھا زخم
شہید ہوں میں تری تیغ کے لگانے کا
غالب نے اسی مضمون کو یوں باندھا ہے ؎
نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو
یہ لوگ کیوں مرے زخمِ جگر کو دیکھتے ہیں
میر اور غالب کے یہ دونوں اشعار ہمیں فارسی کے اِس شعر کی یاد دلاتے ہیں ؎
ہر کس کہ زخم کاریِ مارا نظارہ کرد
تا حشر دست و بازوئے او را دعا کند
غالب کی ابتدائی دور کی شاعری کا بیش تر سرمایہ فارسی میں ہے اور اسی کو وہ ’’نقش ہائے رنگ رنگ ‘‘ کہتے تھے اور اپنے ’’مجموعۂ اردو ‘‘کو ’’بے رنگ‘‘ خیال کرتے تھے ؎
فارسی بیں تابہ بینی نقش ہائے رنگ رنگ
بگذراز مجموعۂ اردو کہ بے رنگِ من است
فارسی میں شعر کہنے کے علاوہ انھوں نے اکثر فارسی اشعار کے ترجمے بھی کیے ہیں، لیکن اشعار میں کہیں سے بھی ترجمہ پن کی بو نہیں آتی۔ ان کے دوسرے اشعار کی طرح یہ اشعار بھی بالکل طبع زاد (Original)معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں وہی سلاست، وہی روانی اور وہی سادگی جلوہ گر ہے جو دوسرے اشعار میں پائی جاتی ہے۔ غالب کے دیوان میں بے شمار اشعار ایسے ملیں گے جو فارسی کا چربہ ہیں، لیکن ان کا اندازِ بیان سہل ہے اور ان میں اتنی برجستگی پائی جاتی ہے کہ گمان ہی نہیں ہوتا کہ یہ فارسی سے ترجمہ کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر فارسی کا یہ شعر ملاحظہ ہو ؎
جانے کہ داشت کرد فدائے تو آذری
شرمندہ از تو گشت کہ جانِ دگر نہ داشت
غالب اسی خیال کو یوں ادا کرتے ہیں ؎
جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
ایک اور شعر ملاحظہ ہو جسے اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ غالب کا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے۔ اصل شعر فسونی تبریزی کا ہے جو یوں ہے ؎
بہ اوچو می رسم آسودہ می شوم ازدرد
ندیدہ حالِ مرا وقتِ بے قراری حیف
غالب کا شعر یوں ہے ؎
اُن کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق
وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے
غالب کے کلام میں سادگی وسادہ بیانی کے ذکر سے ہر گز یہ مراد نہیں کہ اُن کے یہاں اس کے علاوہ کوئی دوسری خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ ان کی شاعری میں شوخی و ظرافت، طنز و مزاح، رندی و سرمستی، کیفیاتِ حسن و عشق، نیز واعظ و جنت کے تذکرے، سبھی کچھ ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ان کا طرزِ بیان اتنا سہل ہے کہ ان مضامین کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔
شعر کو آسان اور عام فہم بنانے کے لیے غالب نے مختلف طریقے (Devices) استعمال کیے ہیں۔ طویل اور پیچیدہ بحروں کی جگہ انھوں نے مختصر اور آسان بحریں استعمال کیں۔ فارسی کی اضافتوں کو کم کیا اور تشبیہات و استعارات بھی وہی استعمال کیے جو عام انسانی فہم سے بالاتر نہ ہوں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں ؎
دلِ ناداں تجھے ہوا کیا ہے
آخر اس درد کی دوا کیا ہے
________
ہے خبر گرم ان کے آنے کی
آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا
________
موت کا ایک دن معین ہے
نیند کیوں رات بھر نہیں آتی
________
کیا وہ نمرود کی خدائی تھی
بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا
________
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے
بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے
________
نظر میں کھٹکے ہے بِن تیرے گھر کی آبادی
ہمیشہ روتے ہیں ہم دیکھ کر در و دیوار
ایک شاعر اور ایک عام انسان کے تخیل میں زمین وآسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ شاعر جس چیز کو دیکھتا اور محسوس کرتا ہے، ایک عام انسان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ غالب کے تخیل کی دنیا ایک دوسری دنیا تھی، جہاں ہر ذہن کی رسائی ناممکن تھی، لیکن جب غالب نے سہل پسندی اختیار کی تو انھوں نے اپنے تخیل کو ایک عام آدمی کے تخیل سے ملا دیا اور روز مرہ کی زندگی کے مشاہدات اور احساسات کو اس طرح پیش کیا کہ وہ دیکھنے والوں کو عجیب نہ معلوم ہوں۔ غالب کی قوتِ مشاہدہ معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتی۔ سبھی جانتے ہیں کہ جب آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے تو اس میں سے ہلکی سی آواز نکلتی ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے، لیکن چوں کہ غالب ایک شاعر تھے، لہٰذا وہ اس سے ایک اور نتیجہ اخذ کرتے ہیں ؎
آگ سے پانی میں بجھتے وقت اٹھتی ہے صدا
ہر کوئی درماندگی میں نالہ سے دوچار ہے
اس شعر میں غالب کا اندازِ بیان اتنا سادہ ہے کہ اسے سہلِ ممتنع کہنا بیجا نہ ہو گا۔
تخیل کی بلند پروازی غالب کے یہاں ضرور پائی جاتی ہے، لیکن اس بنیاد پر ہم انھیں ’فلسفی ‘ نہیں کہہ سکتے، البتہ مفکر ضرور کہہ سکتے ہیں۔ ان کے اشعار ہمیں فکر کی دعوت دیتے ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن کسی پیچیدگی یا الجھن کا شکار نہیں ہونے دیتے۔ شعر ملاحظہ ہو ؎
قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں
موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں
________
غمِ ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج
شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک
کون نہیں جانتا کہ شمع صبح ہونے تک مختلف رنگ بدلتی رہتی ہے۔ کبھی تیز ہو جاتی ہے تو کبھی مدھم ہونے لکتی اور کبھی بجھنے پر آ جاتی ہے، لیکن ہر حال میں وہ صبح تک جلتی رہتی ہے۔ انسان کی زندگی بھی مختلف نشیب و فراز سے ہو کر گذرتی ہے ان سب پریشانیوں اور مصیبتوں سے اسے چھٹکارا اسی وقت ملتا ہے جب وہ آخری سانسیں لیتا ہے۔
غالب کے کلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں اختصار پایا جاتا ہے۔ وہ بڑے سے بڑا مضمون بھی نہایت اختصار کے ساتھ ایک شعر میں نظم کر دیتے ہیں، لیکن اس سے یہ ہر گز نہیں سمجھنا چاہیے کہ شعر کوئی پہیلی یا معما بن کر رہ جاتا ہے۔ شعر میں کوئی نہ کوئی لطیف اشارہ ایسا ضرور موجود ہوتا ہے جو شعر کی تفہیم میں معاون ہوتا ہے، اور اس طرح شعر مشکل نہیں معلوم ہوتا۔ یہ شعر ملاحظہ ہو ؎
تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم !
میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے
________
قفس میں مجھ سے رودادِ چمن کہتے نہ ڈر ہمدم
گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو
اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کے اشعار میں غالب نے دریا کو کو زے میں بند کر دیا ہے، لیکن ذہن اگر ذرا سابھی بیدار ہو تو شعر کا سمجھنا قطعی مشکل نہیں۔
غالب کے کلام میں عاشقانہ مضامین کی اتنی اہمیت نہیں جتنی کہ عاشقانہ مضامین میں ان کی شوخی و ظرافت کے امتزاج کی ہے۔ یہ میدان گویا انھی کے لیے مخصوص ہے۔ ان کی شوخی و ظرافت کا انداز بالکل فطری ہے۔ غالب کا طنز بھی بہت سادہ اور براہِ راست ہوتا ہے۔ سادگی کے باعث اس میں ایک مخصوص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، مثلاً ؎
چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسدؔ
آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے
________
مجھ تک کب ان کی بزم میں آیا تھا دورِ جام
ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں
رندانہ مضامین کی بھی ان کے یہاں کمی نہیں۔ خمریات پر ان کے اشعار ان کی بہترین شاعری کا نمونہ ہیں۔ وہ شراب کی لذت سے آشنا تھے اور شراب انھیں بے حد عزیز تھی۔ اسی لیے انھوں نے خمریات سے متعلق عجیب عجیب مضامین پید ا کیے ہیں۔ شراب سے والہانہ محبت کے اظہار میں بھی انھوں نے سہل پسندی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان کے یہ اشعار دیکھیے ؎
گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے
رہنے دو ابھی ساغر و مینا مرے آگے
________
جاں فزا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آگیا
سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگِ جاں ہو گئیں
________
میں نے مانا کہ کچھ نہیں لیکن
مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے
________
مے ہی پھر کیوں نہ مَیں پیے جاؤں
غم سے جب ہو گئی ہو زیست حرام
غالب نے واعظ و زاہد پر بھی خوب خوب طنز کیے ہیں اور شراب کے ذکر کے ساتھ جنت و دوزخ کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ان تمام مضامین کے بیان میں سادگی و سہل پسندی کی نمایاں خصوصیت کو انھوں نے ہر جگہ برقرار رکھا ہے ؎
جانتا ہوں ثوابِ طاعت و زہد
پر طبیعت ادھر نہیں آتی
________
وہ چیز جس کے لیے ہو ہمیں بہشت عزیز
سوائے بادۂ گلفام و مشک بو کیا ہے
________
کہاں میخانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ
پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے
غالب حسن کے شیدائی تھے۔ ان کے کلام میں بیشتر اشعار حسن کے موضوع پر ہیں۔ حسن کا تذکرہ جہاں بھی انھوں نے کیا ہے خلوص وسادگی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہے۔ وہ حسن کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور ایک خاص کیفیت میں کھو جاتے ہیں، لیکن اپنے بیان کی سادگی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وہ سچائی اور سادگی کے ساتھ وہی بیان کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں ؎
یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں
غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے
شکنِ زلفِ عنبریں کیوں ہے
نگہِ چشمِ سرمہ سا کیا ہے
________
حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد
بارے آرام سے ہیں اہلِ جفا میرے بعد
غالب محبوب کے حسن سے زیادہ اس کی اداؤں اور شوخیوں سے متاثر نظر آتے ہیں، لیکن اس تاثر کا اظہار بھی وہ اسی انداز میں کرتے ہیں ؎
اس نزاکت کا بُرا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا
ہاتھ آئے تو انھیں ہاتھ لگائے نہ بنے
غالب کی سہل پسندی اور سادہ بیانی جسے سطورِ بالا میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کی زندگی اور شاعری کے اختتامی دور سے زیادہ تعلق رکھتی ہے۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے جو محتاجِ دلیل نہیں کہ کسی بھی شاعر کا اہم ترین رنگ یاسب سے زیادہ قابلِ توجہ اسلوبِ بیان وہ ہوتا ہے جو اس کی عمر کی پختہ ترین منزل یاسب سے زیادہ ترقی یافتہ دور سے تعلق رکھتا ہے، کیوں کہ مشقِ سخن، طرزِ فکر اور قوتِ بیان کی اس منزل میں پہنچ کر وہ اپنی معراج کو چھو لیتا ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم غالب کے صرف ابتدائی دور کے ہی کلام کو مدِ نظر رکھ کر اس بات کو دہراتے رہیں کہ وہ ایک نہایت مشکل پسند شاعر تھے، بلکہ کیوں نہ ہم ان کی عمر کے بہترین دور کے کلام کو مدِ نظر رکھتے ہوئے انھیں ایک ایسا شاعر تسلیم کریں جو سہولتِ بیان اور سادگیِ اظہار پر اعلیٰ ترین قدرت رکھتا تھا اور اسی بنا پر ایک سہل پسند اور سادہ بیان شاعر قرار دیے جانے کا بھی حق رکھتا تھا۔
٭٭٭
پنڈت آنند نرائن ملا کے نثری افکار
پنڈت آنند نرائن ملا اردو کے ان بزرگ ترین ادیبوں میں ہیں جنہوں نے شعر کو اپنے تخلیقی اظہار کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وہ اردو ادب میں بہ حیثیت شاعر ایک ممتاز درجہ رکھتے ہیں گزشتہ نصف صدی کے دوران انھوں نے اردو کے شعری سرمایے میں جو گراں قدر اضافے کیے ہیں۔ ان کی وجہ سے اردو ادب کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن وہ اگر ’’جوئے شیر‘‘ نہ لکھتے اور ’’میری حدیث عمر گریزاں ‘‘ تخلیق نہ کرتے تب بھی ان کا یہ جملہ کہ ’’میں مذہب چھوڑ سکتا ہوں لیکن زبان نہیں چھوڑ سکتا‘‘، انھوں نے اردو دنیا میں حیات دوام بخشنے کے لیے کافی تھی۔ تقریباً ربع صدی گزر جانے کے بعد بھی ان کا یہ جملہ زبان رد خاص و عام ہے، ملا صاحب یہی بات اگر شعر میں کہتے تو سمجھا جاتا کہ وہ غلو یا حسن بیان سے کام لے رہے ہیں۔ بہت سے اہل نظر اسے خود کلامی پر محمول کرتے۔ ممکن ہے بعض ناقدان شعرا سے محض داخلی اور تاثراتی اظہار کا نام دے کر اس سے صرف نظر کر جاتے۔ لیکن نثر کے پیرایے میں کہی گئی بہ ظاہر یہ سادہ سی بات بہتوں کے دلوں کو چھو گئی۔ یہ ایک ایسی فکر تھی جس نے کتنوں کا چونکا دیا۔ اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا واقعی زبان کو عقیدے پر ترجیح دی جا سکتی ہے ممکن ہے مہ ایک مخصوص طرز فکر رکھنے والے طبقے کو ملا صاحب کے اس بیان سے اتفاق نہ ہوا اور وہ عقیدے ہی کو سب کچھ سمجھتا ہو، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ملا صاحب کا یہ بیان اردو زبان سے ان کی گہری عقیدت، سچی محبت اور والہانہ لگاؤ کا غماز ہے۔ ملا صاحب کو اردو سے بے پناہ عشق ہے۔ وہ اردو کو ٹوٹ کر چاہنے والوں میں ہیں خواہ اس کے لیے انھیں مذہب اور عقیدے کو ہی کیوں نہ قربان کر دینا پڑے۔
مجھے ملا صاحب کی اس نُدرت فکر نے اس حد تک متاثر کیا کہ میں ان کی شخصیت، مزاج اور فکر کو بہت قریب سے مطالعہ کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اگر چہ ملا صاحب کی شخصیت کی جھلک اور ان کے مزاج اور فکر کی عکاسی ان کی شاعری میں پائی جاتی ہے لیکن شاعری طبعاً تخلیقی ہونے کی وجہ سے بیش تر داخلی کیفیات اور جمالیاتی تجربات تک محدود رہتی ہے اور خارجی دنیا کے معاملات سے اس کا ساتھ بہت کم رہتا ہے۔ خارجی علل و عوامل کو سمجھنے کا نثر بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ ملا صاحب ایک کامیاب شاعر ہونے کے علاوہ ایک جہاں دیدہ انسان اور دانشور بھی ہیں انھوں نے اپنے بعض خیالات کی ترویج کے لیے نثر کا سہارا لیا ہے ملا صاحب کا نثری سرمایہ بہت قلیل ہے جو چند مضامین، خطبات اور ریڈیائی تقاریر پر مشتمل ہے۔ لیکن ان میں گہری لسانی فکر، دانشورانہ سوجھ بوجھ اور سماجی و تہذیبی شعور کی جھلک پائی جاتی ہے۔ بعض مضامین میں گہری تنقیدی بصیرت کا دیکھنے کو ملتی ہے۔
ملا صاحب کی نثر نگاری کا آغاز ایک ریڈیائی ٹاک سے ہوتا ہے جس کے محرک نیاز فتحپوری تھے۔ اس ٹاک کا عنوان تھا ’’غالب کے کلام میں تصوف‘‘ اور یہ ۱۹۳۸ء میں آل انڈیا ریڈیو، دہلی سے نشر ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے ان کی ریڈیائی ٹاکس کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور ۱۹۷۵ء تک بقول ملا صاحب ان کی ڈھائی تین سو ٹاکس نشر ہوئیں لیکن افسوس کہ ان میں سے بیشتر ٹاکس ضائع ہو گئیں اور جو محفوظ رہ گئیں وہ ان کے مجموعے ’’کچھ نثر میں بھی‘‘ میں شامل ہیں لیکن ان کی تعداد صرف دس ہے ریڈیائی ٹاکس کے بعد ملا صاحب کے خطبات کا نمبر آتا ہے، جن دہلی یونیورسٹی کے نظام خطبات، انجمن ترقی اردو (ہند) کی اردو کانفرنس اور جامعہ اردو، علی گڑھ کے جلسہ تقسیم اسناد کے صدارتی خطبات کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ ملا صاحب کی ریڈیائی ٹاکس ہوں یا ان کے خطبات و مضامین یہ زیادہ تر قلم برداشتہ لکھے گئے ہیں۔ کیوں کہ پیشہ ورانہ مصروفیات کی وجہ سے ملا صاحب کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ پہلے سے انھیں لکھتے، صاف کرتے، ان پر نظر ثانی کرتے یا ان کی نقول کرتے، ملا صاحب بنیادی طور پر ایک شاعر ہیں۔ اپنے مخصوص مزاج یا محض عدیم الفرصتی کی بنا پر انھوں نے نثر کی طرف وہ توجہ نہیں دی جس کی وہ متقاضی تھی۔ انھیں خود بھی اس کا اعتراف ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں :
’’دراصل میں نے نثر نگاری کی طرف کبھی کوئی توجہ نہیں کی۔ شاید غیر شعوری طور پر میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے یہ صلاحیت مجھ میں نہیں۔ شاعری میں تو روایات کی بیساکھی مل جاتی ہے، آہنگ کے سہارے کام آئے ہیں لیکن نثر لکھنے والے کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ساری مسافت اپنے ہی بل بوتے پر طے کرنا پڑتی ہے۔ نثر نگاری (سطحی افسانہ نویسی اور انشائے لطیف کی اور بات ہے) اچھی خاصی علمی واقفیت چاہتی ہے‘‘
ملا صاحب کے نثری افکار کو تین زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ۱-دانشورانہ افکار، ۲-انتقادی افکار اور ۳-لسانی افکار۔ دہلی یونیورسٹی کے نظام خطبات ملا صاحب کے دانشورانہ افکار کی بہترین مثال پیش کرتے ہیں۔ ان خطبات کے مطالعے سے ملا صاحب کی اپنی فکر کا پتا چلتا ہے وہ کسی موضوع پر اظہار خیال کے لیے موٹی موٹی کتابوں کی ’’چھان بین‘‘ اور ’’وسیع مطالعے‘‘ کی ضرورت پر زیادہ زور نہیں دیتے اور نہ اس کے لے وہ ’’علم کی گہرائیوں میں ڈوبنے‘‘ کے قائل ہیں بلکہ وہ اپنے ’’احساس اور شعور کی تربیت‘‘ سے ایک اپنا انداز فکر پیدا کرتے ہیں جو لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ ملا صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں :
’’میں وسیع مطالعہ کا قائل ہوں لیکن اس سے کہیں زیادہ اس بات کا قائل ہوں کہ انسان خود ان موضوعات پر سوچے اور غور کرے جن کے بارے میں وہ دوسروں کے ذہن سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے‘‘۔
دہلی یونیورسٹی کے نظام خطبات کے تحت ’’عالمی نظام میں انسان کے بنیادی حقوق‘‘ کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے۔ انھوں نے اپنی جس عمیق فکر کا ثبوت دیا ہے اس سے نہ صرف موضوع پر ان کی مضبوط گرفت کا پتا چلتا ہے بلکہ دنیا کی تاریخ و تہذیب اور سیاسی نظام کی طرف ان کے دانشورانہ رویے کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور آزادی، مساوات اور اخوت کے بارے میں ان کی اپنی رائے کا بھی پتا چلتا ہے۔ اس ضمن میں ان کا یہ فکر پارہ ملاحظہ ہو:
’’واقعہ یہ ہے کہ انسان نے جینا تو پیدائش کے روز ہی سیکھ لیا تھا، کیوں کہ جہد بقا اس کی فطرت کا تقاضا تھا، لیکن دوسروں کو جینے دینے کا گر وہ آج تک نہ سیکھ سکا۔ اور زندگی کے سارے غم اور پریشانیاں، سارے جبر اور خوں ریزیاں، ساری محرومیاں اور ناانصافیوں اسی کوتاہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں ‘‘۔
آج جب کہ تخریبی قوتیں ہر طرف اپنا سر اٹھا رہی ہیں اور تعمیری قوتوں کو پنپنے سے روک رہی ہیں ملا صاحب کا ذیل کا اقتباس کتنا معنی خیز بن جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ ان کی نثر کا ایک خوب صورت نمونہ بھی ہے، ملاحظہ ہو:
’’تعمیری اور تخریبی قوتیں ایک ہی اندازسے اپنا کام نہیں کرتیں۔ بجلی زلزلے، آندھی، طوفان ایک صہیب شور اور گرج لے کر آتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وقتی ہوتے ہیں۔ زندگی یا وجدان کی لائی ہوئی آفات کے آگے بڑھتی ہے اور یہ تعمیر ی قوتوں سے شکست کھا کر غائب ہوتے ہیں۔ برخلاف اس کے تعمیری قوتیں اتنی خاموشی سے کام کرتی ہیں کہ لوگوں کی نظر کافی دیر تک ان کی طرف نہیں جاتی۔ رات کس طرح دن بن جاتی ہے موسم کس طرح بدل جاتا ہے، کلی کس طرح پھول بن جاتی ہے، فضا کی نمی کس طرح شبنم کا قطرہ بن کر پھول کی پنکھڑی پر ستارہ جڑ دیتی ہے۔ یہ باتیں بجلی اور طوفان سے کہیں زیادہ اہم اور دیر پا رہیں ‘‘۔
اس قسم کے نمونے ان کی نثر میں جا بجا پائے جاتے ہیں۔
ملا صاحب کے نثری افکار میں ان کے انتقادی افکار کو بھی بے حد اہمیت حاصل ہے۔ ملا صاحب اگر چہ پیشہ ور نقاد نہیں لیکن غالب، سرشار، چکبست، اثر و سراج نیز سردار جعفری کے مجموعہ کلام ’’پیراہن شرر‘‘ پران کی جو تحریریں ملتی ہیں۔ ان کی تنقیدی بصیرت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ملا صاحب کی تنقیدی تحریروں کو تاثراتی تنقید کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ کیوں کہ کسی فن پارے کو پڑھ کر جو تاثرات وہ اپنے ذہن پر مرقسم کرتے ہیں اور بعدہٗ قاری تک منتقل کرتے ہیں اس میں ان کے وجدان کو کافی دخل ہوتا ہے۔ اگر ملا صاحب کی تنقیدی تحریروں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ ان کے جذباتی رد عمل کا نتیجہ ہیں تو بے جا نہ ہو گا۔ ملا صاحب کے تنقیدی رویے کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ وہ محض فن پارے کی تحسین سے کام نہیں لیتے بلکہ ان کی خامیوں کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ یہاں صرف ایک اقتباس نقل کرنا کافی ہو گا۔ سرشارؔ کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں :
’’لیکن فنی اعتبار سے ’’فسانہ آزاد‘‘ میں بے شمار خامیاں ہیں۔ افسانے کا نہ تو قصہ ہی کوئی خاص دلکش ہے اور نہ اس میں وہ سلسلہ اور ربط ہے جو ایک افسانے کے لیے لازمہ ہے۔ بہت سے باب ایسے ہیں جن میں محض فضول اور غیر متعلق باتوں کا ذکر ہے۔ کردار نگاری میں بھی نفسیات کے اعتبار سے سنگین خامیاں ہیں۔ سرشارؔ نہ تو مفکر تھے اور نہ ماہر نفسیات۔ انھوں نے انسان کے دل و دماغ کا گہرا مطالعہ نہیں کیا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی شوخی اور ظرافت سے روتوں کو تو ہنساتے تھے لیکن نرم دل سے نرم دل کو رلا نہ سکتے تھے۔ ان کے افسانوں میں درد…بالک معدوم ہے‘‘
ملا صاحب کی نثری تحریروں کا ایک خاص عنصر ان کی لسانی فکر ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے لسانی افکار کو ان کے دوسرے تمام نثری افکار پر اولیت حاصل ہے تو بے جا نہ ہو گا۔ اردو سے ان کے والہانہ عشق کا ذکر شروع میں آ چکا ہے، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ملا صاحب کے لیے زبان مذہب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آج سے ۲۷سال قبل انجمن ترقی اردو (ہند) کے زیر اہتمام منعقدہ اردو کانفرنس کے اجلاس میں صدارتی تقریر کرتے ہوئے انھوں نے بڑی جرأت کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ ’’میں مذہب چھوڑ سکتا ہوں لیکن زبان نہیں چھوڑ سکتا‘‘۔ ان کے اس اعلان نے اردو تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی تھی اور محبان اردو کے دلوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔
اردو کے بارے میں ملا صاحب کا موقف بالکل واضح ہے وہ اردو کو اسی ملک کی زبان سمجھتے ہیں ’’جو تقسیم ہند کے بعد بھی کروڑوں شہریوں کی مادری زبان ہے‘‘۔ ان کے نزدیک اردو قومی یکجہتی کا ایک نشان اور باہمی میل جول کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ ملا صاحب کی مادری زبان اردو ہے۔ وہ اردو لکھنا پڑھنا اور بولنا اپنا آئینی حق سمجھتے ہیں۔ انھوں ایک جگہ لکھا ہے:
’’اردو کا سوال میرے لیے اپنی مادری زبان کا سوال ہے جب تک اس دیس میں جمہوری حکومت قائم ہے اور میری دعا ہے کہ روز بروز یہ مضبوط ہو اس وقت تک مجھے آئین نے کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں اپنی مادری زبان پڑھوں، لکھوں اور بولوں اور اسی زبان میں اپنے جذبات اور افکار کو پیش کروں ‘‘۔
ملا صاحب نے مادری زبان کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ ان کے خیال میں انسان اپنی مادری زبان ہی میں اپنے دل و دماغ کی نقاب کشائی تخلیقی حسن کے ساتھ صحیح اور پورے طور پر کر سکتا ہے… کوئی انسان جس سے اس کی مادری زبان چھین لی جائے وہ اپنا پورا قد نہیں پاتا اور وہ اس پودے کی مانند ہوتا ہے جو ناساز گار آب و ہوا کی وجہ سے ٹھٹھ کر رہ جائے‘‘۔ ان کے نزدیک مادری زبان محض ایک زبان ہی نہیں ہوئی۔ یہ صدیوں کی تاریخ، تہذیب، معاشرت اور انداز فکر کا ملاجلا نتیجہ ہوتی ہے‘‘۔ اور جہاں تک اردو کا تعلق ہے، یہ ملا صاحب کی ذات کا آئینہ ہے ان کی میراث ہے، ان کی تاریخ ہے اور ان کی زندگی ہے۔
ملا صاحب کی لسانی فکر کے تجزیے سے پتا چلتا ہے کہ وہ اردو تحریک کے ایک فعال قلم کار ہی نہیں بلکہ ایک نڈر سپاہی بھی ہیں۔ ملا صاحب نے ہر جگہ اور ہر موقع پر اردو کی وکالت بڑی بے باکی کی ساتھ کی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں انھوں نے جہاں حکومت کے جبر اور عوام کے تعصب کا ذکر کیا ہے وہیں حامیان اردو کے خون جگر کی کمی کا بھی شکوہ کیا ہے۔
ملا صاحب نے ایک طویل عرصے تک اردو تحریک کی علم برادری کی ہے وہ انجمن ترقی اردو ہند، کے صدر رہے۔ انجمن کی اتر پردیش کی ریاستی شاخ کے بھی صدر رہے جامعہ اردو علی گڑھ کے نائب امیر جامعہ رہے۔ ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اردو کو اس کے جائز حقوق مل جائیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انھوں نے تین قسم کے محاذ کے قیام پر زور دیا ہے۔ یعنی عوامی محاذ، تنظیم محاذ اور آئینی محاذ، عوامی محاذ کا مقصد کو محبان اردو کے نظریے کی صحت اور ان کی حق تلفی کی اہمیت کا اہمیت کا احساس دلانا تھا نیز اردو کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں یا جو جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی تھیں ان کی تردید کرنا تھا۔ اردو کے حقوق کے مطالبے کے لیے ملا صاحب نے تنظیمی محاذ کے قیام پر شدت کے ساتھ زور دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محبان اردو کو جوش اور جذبات سے کام لینے کے بجائے ایک منظم تحریک کی شکل میں اردو کے حقوق کا مطالبہ کرنا کرنا چاہیے۔ آئینی محاذ کے قیام کا مقصد مرکزی حکومت نیز ریاستی حکومتوں کی توجہ اپنے بنیادی حقوق کی پامالی کی طرف برابر دلاتے رہنا تھا۔ ملا صاحب نے آج سے ۳۰ سال قبل جن تین محاذوں کے قیام کی اہمیت پر زور دیا تھا ان کی ضرورت آج بھی ہے کیوں کہ اردو کے مسائل جہاں تھے وہیں ہیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ آج تعلیمی اداروں سے اردو رخصت ہوتی جا رہی ہے اور نئی نئی نسل اردو سے بالکل نابلد ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج اردو کے لیے ایک اور محاذ کھولا جائے اور وہ تعلیمی محاذ ہو۔ ملا صاحب نے تعلیمی سطح پر اردو کے نفاذ کی دشواریوں کو بہت پہلے بھانپ لیا تھا۔ انھوں نے اکتوبر ۱۹۶۳ء میں ریاستی لسانی کنونشن اتر پردیش کے انعقاد کے موقع پر اپنی صدارتی تقریر میں اردو کے ساتھ حکومت اتر پردیش کے غیر منصفانہ رویے کی سخت تنقید کی تھی اور یہ بانگ دہل پر اعلان کیا تھا کہ ’’سہ لسانی فارمولے میں جو تیسری زبان انتخاب کرنے کا طریقہ رکھا گیا ہے وہ اردو کے لیے سم قاتل سے کم نہیں ‘‘۔
۱۹۶۱ء میں جب تمام ریاستوں کے وزرائے اعلا و مرکزی حکومت کے وزیر کی میٹنگ میں طلبہ کا تین زبانیں پڑھانے کا فیصلہ ہوا تھا تو فیصلہ ہوا تھا تو ملا صاحب نے اس فارمولہ نے کا دل سے خیر مقدم کیا تھا کیوں کہ ہر اس طالب علم کو جس کی مادری زبان اردو تھی یا جو اردو پڑھنا پسند کرتا تھا یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ اردو بحیثیت تیسری زبان کے پڑھے۔ لیکن اتر پردیش کی حکومت نے سہ لسانی فارمولہ کے الفاظ کے کھلے مفہوم کے خلاف جو تاویل پیش کی تھی اس سے ملا صاحب کو سخت تکلیف پہنچی تھی وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ’’ہماری ریاستی حکومت نہ آئین کی پروا کرتی ہے اور نہ انصاف کی اور لسانی تعصب کا شکار ہو چکی ہے‘‘۔ حکومت اتر پردیش نے سہ لسانی فارمولہ کی دفعہ (ب) کے تحت کی زبانوں میں سنسکرت کو شامل کر کے اردو کے ساتھ سخت ناانصافی کی تھی۔ ملا صاحب کے خیال میں سنسکرت چوں کہ ایک کلاسیکی زبان ہے اس لیے ملک کی دوسری زندہ زبانوں میں سنسکرت کا شمار کرنا اصولاً تھا۔ اور یہ محض اس لیے کیا گیا تھا کہ ’’اس کو اردو پڑھانے کا ایک لغو بہانہ مل جائے‘‘۔
ملا صاحب کی لسانی تحریروں کے تجزیہ سے پتا چلتا ہے کہ لسانی مسائل پر ان کی نظر بہت گہری تھی اور وہ دو ٹوک بات کہنے میں ذرا بھی تامل نہیں کرتے تھے خواہ وہ حاکم وقت کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ ملا صاحب نے گزشتہ نصف صدی کے دوران جس جرأت و بے باکی اور جس مجاہدانہ عزم کے ساتھ اردو کی لڑائی لڑی ہے اس کی مثال اردو تحریک کی تاریخ میں بہت کم ملے گی۔
٭٭٭
رشید احمد صدیقی کی آخری تحریر ’’عزیزان علی گڑھ‘‘
’’عزیزان علی گڑھ‘‘ رشید احمد صدیقی کی آخری تحریر ہے جس کا ڈول تو ۱۹۶۷ء میں پڑا تھا، لیکن جسے وہ اپنے انتقال (۱۵؍ جنوری ۱۹۷۷ء) سے ایک دن پہلے تک درست فرماتے رہے تھے لیکن صدافسوس کہ ان کی شدید خواہش اور کوشش کے باوجود یہ تحریر ان کی زندگی میں کتابی صورت میں شائع نہ ہوسکی۔ جب بھی اس کے چھپنے کی امید پیدا ہوتی معاملہ کسی نہ کسی وجہ سے کھٹائی میں پڑ جاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ تحریر اُن کی مرضی سے ’’قومی آواز‘‘(لکھنؤ) کے ہفتہ وار ضمیمے میں ۲۶قسطوں میں شائع ہوئی۔ اس کے کچھ اجزاء اُن کی عنایت سے صحابہ ’فکر و نظر‘ (علی گڑھ ملسم یونیورسٹی) میں بھی چھپے ’’عزیزان علی گڑھ‘‘ کی شان نزول کے بارے میں رشید صاحب یوں رقم طراز ہیں :
’’۱۹۶۷ء میں پروفیسر ڈاکٹر عبد العلیم صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو کر تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ موصوف اس ادارے کی صد سالہ جوبلی منانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسکیم کی داغ بیل ڈال دی گئی۔ کچھ کام بھی ہونے لگا تھا لیکن کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ مجوزہ تقریب ملتوی کر دی گئی۔ جوبلی کے ساتھ یہ خیال دل میں آیا کہ اپنے طلبہ عزیزان علی گڑھ کو ایک خطبہ دوں گا۔ لکھنا شروع کر دیا تھا پھر یہ ہوا کہ جوبلی ملتوی ہو گئی لیکن خطبہ کا لکھا جانا بند نہ ہوا اور طویل وقفوں کے ساتھ یہ مشغلہ جاری رہا کچھ دنوں بعد معلوم ہوا کہ لذیذ نہ ہونے کے باوجود حکایت دراز ہو گئی‘‘۔
مذکورہ اقتباس رشید احمد صدیقی کی اس تحریر سے نقل کیا گیا ہے جو ’’کچھ ا سبے ربطی شیرازہ اجزائے حواس کے بارے میں ‘‘ کے عنوان سے بطور تعارف خطبہ عزیزان علی گڑھ کی ابتدا میں درج ہے۔
’’عزیزان علی گڑھ‘‘ کی شان نزول کا ایک اور حوالہ ہمیں رشید صاحب کے اس خط میں ملتا ہے جو انھوں نے ۱۶؍ جولائی ۱۹۷۲ء کو ڈاکٹر گیان چند جین کو لکھا تھا:
’’آپ نے جس طرح میرے ناتمام خطبہ ’’عزیزان علی گڑھ‘‘ کو پسند اور اس ضمن میں مجھے جس خلوص سے یاد فرمایا ہے اس سے بہت خوش اور شکر گذار ہوں … خطبہ کا جو حصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے (وہ)کل کا تقریباً ایک چوتھائی ہے جس کے اقتباسات مدیر ’’فکر و نظر‘‘ نے جہاں تہاں سے لے کر شائع کر دیے کاش کوئی صورت ایسی نکل سکتی کہ پورا خطبہ ناظرین کے مطالعہ میں آسکتا۔ یہ خطبہ کہیں پڑھا نہیں گیا۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ کئی سال گذرے مسلم یونیورسٹی کی جبلی منانے کی تحریک سامنے آئی۔ خیال آیا کہ اس موقع کے لیے ایک خطبہ لکھوں گا جس کے مخاطب یونیورسٹی کے طلبہ ہوں گے جبلی کی تحریک ملتوی ہو گئی لیکن خطبہ کا کام وقتاً فوقتاً جاری رہا۔ اب دیکھتا ہوں تو وہ بہت طویل ہو گیا، اس کا حشر کیا ہو گا کچھ نہیں معلوم‘‘۔
جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے ہے خطبہ ’’عزیزان علی گڑھ ‘‘ لکھنؤ کے اخبار ’’قومی آواز‘‘ کے ہفتہ وار ضمیمے میں قسط وار شائع ہوا تھا۔ اس کی ہر قسط کے ساتھ سرخیاں اور عنوانات‘‘ بھی قائم کیے گیے تھے لیکن کتابی شکل میں شائع کرتے وقت نہ جانے کیوں اس کے عنوانات حذف کر دیے گیے۔
رشید صاحب کی روح کو ’’عزیز ان علی گڑھ‘‘ کی اشاعت سے کتنا سکون ملا ہو گا، اس کا اندازہ ہمیں فصیح احمد صاحب کی اس تحریر سے ہوتا ہے جو ’’قصہ عزیزان علی گڑھ کے چھپنے کا‘‘ کے عنوان سے زیر نظر کتاب میں بطور دیباچہ شامل ہے۔ اسی کے ساتھ فصیح صاحب کی ایک اور تحریر بھی چھپی ہے جس میں انھوں نے اپنے ’’ماموں میاں ‘‘ (رشید احمد صدیقی مرحوم) کے دم وپیسی کی روداد بڑے پر اثر انداز میں بیان کی ہے جس کے ایک ایک لفظ سے رشید صاحب سے اُن کی محبت اور عقیدت ٹپکتی ہے۔
رشید صاحب کے انتقال کے بعد سے اب تک ’’عزیزان علی گڑھ‘‘ کا مسودہ فصیح احمد صدیقی کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اسے اردو کی بدنصیبی کہنا چاہیے کہ تیرہ سال تک اس کی طباعت کا انتظام یہاں نہ ہوسکا۔ چنانچہ اپنے دورہ علی گڑھ کے دوران لطیف الزماں نے جیسے ہی اس کے مسودے کو دیکھا اسے زیر طبع سے آراستہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ انھوں نے نہایت تشویق سے اس کے منتشر اجزاء کو یکجا کیا۔ لفظ بہ لفظ اور بڑی محنت اور وقت نظر کے ساتھ مدون کر کے اور کلیۃ ً اپنے اخراجات سے طبع کروا کر اسے قارئین کے سامنے پیش کر دیا۔ لطیف صاحب تمام دنیا کے شکریے کے مستحق ہیں جن کی سعی و کاوش سے یہ مقتدر علمی کام انجام کو پہنچا۔ اس طرح رشید ساحب جو حسرت لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گیے تھے اس کی تکمیل کا سامان انھوں نے بہ طریق احسن بہم پہنچا دیا۔
(۲)
خطبہ ’’عزیزان علی گڑھ‘‘ کا موضوع ’’علی گڑھ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے اور ختم بھی اس کے ذکر پر ہوتا ہے۔ اس کے مخاطب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبا ہیں جن سے وہ اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی کہ علی گڑھ سے ان کو محبت تھی۔ اس خطبے کا انداز غیر رسمی (Informal)ہے، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، اور رشید صاحب علی گڑھ کے حوالے سے سرسید احمد خاں، علی گڑھ تحریک، ایم، اے، او کالج، مسلمانوں کی زبوں حالی، اردو کی کسمپرسی، تحریک آزادی اور ہم عصر سیاسی و سماجی میلانات کا ذکر بڑی فہم و فراست اور ذہنی بصیرت کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی ضمن میں اصغرؔ، حالیؔ، اقبال، غالبؔ اکبر الہ آبادی اور دیگر شعراء کا بھی ذکر آتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنے اصل موضوع سے ہٹتے ہیں تو جنسیت اور ہپی ازم تک کا ذکر کر جاتے ہیں ’’عزیزان علی گڑھ‘‘ کو بادی النظر میں ہم چند منتشر خیالات کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں لیکن بہ نظر غائر دیکھا جا سکتا ہے تو اس کا ہر خیال اپنی جگہ انتہائی جامعہ اور Compactنظر آتا ہے۔ وہ جو ذکر بھی چھیڑتے ہیں اس کے بارے میں اپنی ٹھوس اور مدلل رائے پیش کرتے ہیں، وہ صحیح بات کہنے اور اپنے موقف پر اٹل رہنے میں ذرا بھی جھجھک محسوس نہیں کرتے خواہ اس کے لیے انھیں دوسروں کی خشمگیں ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ رشید صاحب چیزوں کووسیع تناظر میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ اردو یونیورسٹی کی تحریک کی مخالفت اور مسلم یونیورسٹی ترمیمی بل ۱۹۷۲ء کی مذمت اس کی بین مثالیں ہیں۔
خطبہ ’’عزیزان علی گڑھ‘‘ پورے دس سال (۱۹۶۷ء تا۱۹۷۷ء) کے دوران وقفے وقفے سے لکھا گیا۔ یہ رشید صاحب کی زندگی کی آخری دہائی تھی جو کلیتہً علی گڑھ کے لیے وقف ہو کر رہ گئی تھی۔ رشید صاحب کی اس دور کی تحریروں کو دیکھ کر مسعود حسین خاں نے انھیں ’’علی گڑھ نگار کو بہت پیچھے چھوڑ چکے تھے اور صرف علی کے موضوعات پر قلم اٹھاتے تھے۔ مسعود حسین خاں لکھتے ہیں :
’’ان کا قلم ابھی تک نہیں تھکا تھا۔ تابڑ توڑ وہ علی گڑھ اور اس سے متعلق موضوعات پر لکھ رہے تھے۔ یہ تحریر یں جا بجا چھپتی بھی رہیں، لیکن اب وہ مزاح اور طنز نگار نہیں تھے خاکہ نگاری بھی چھوڑ دی تھی وہ اب علی گڑھ نگار تھے۔ کچھ ماضی کی یادیں کچھ حال کے مناظر اور کچھ مستقل کے بارے میں پیشین گوئیاں۔ موجودہ علی گڑھ کی جانب سے مضطرب رہتے، اسی شدت سے ماضی کے علی گڑھ کی جانب بازگشت کرتے‘‘۔
(رقعات رشید صدیقی، مرتبہ مسعود حسین خاں، ص۱۳)
اس اقتباس کے تناظر میں ’’عزیزان علی گڑھ‘‘ کا بخوبی مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے مطالب تک بہ آسانی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ رشید صاحب کا علی گڑھ سے والہانہ عشق اظہر من الشمس ہے۔ انھیں سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، ہمہ وقت علی گڑھ کا خیال رہتا تھا، رشید صاحب نے علی گڑھ میں اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ گذارا تھا اور اپنی بہترین صلاحیتیں اس کی نذر کی تھیں۔ وہ خود فرماتے ہیں :
’’ایک آدھ سال اور جیا تو علی گڑھ کی تابعداری، ترفع اور تحفظ میں اپنی بساط کے مطابق اپنی بہترین صلاحیتوں کو صرف کرتے ہوئے مسلسل ساٹھ سال ہو جائیں گے‘‘۔
(عزیزان علی گڑھ‘‘ ص۴۱)
رشید صاحب ہائی اسکول کے بعد ۱۹۱۵ء میں علی گڑھ۔ خود انھیں کے الفاظ میں :
’’یہ وہ زمانہ تھا جب کالج اپنی اعلیٰ روایات اور اعلیٰ شخصیتوں کی گراں مائگی، مغربی تعلیم، مشرقی تہذیب اور بے مثل رواداری، بلند نظری اور خیرسگالی کا ایسا نمونہ پیش کر رہا تھا جو ملک کے کسی تعلیم، علمی، مغربی ادارہ میں نہیں ملتا تھا، آج بھی مفقود ہے‘‘۔
(عزیزان علی گڑھ‘‘ ص۴۰)
رشید صاحب چاہتے تھے کہ یہ اعلیٰ قدریں علی گڑھ کے طلبہ میں پھر سے پیدا ہوں، اور اگر سچ پوچھا جائے تو ان قدروں کا زوال و فقدان یا پامالی ہی خطبہ ’’عزیزان علی گڑھ‘‘ کا متحرک بنی۔ رشید صاحب نے خطبے کے آغاز میں اس طرف یوں اشارہ کیا ہے:
’’جس تہذیب کے کھنڈر پر، جن اقدار و عزائم کو سامنے رکھ کر، جن سر آمد روزگار نے علی تعمیر کیا تھا اور جس علی گڑھ نے اپنے فرزندوں کو زندگی اور زمانے کے بڑے بڑے چیلنج کو قبول کرنے کا حوصلہ دیا، جن کی تاریخ اور تقدیر کو اس نے ان کے لیے دریافت کیا اور تب و تاب دی، اس کو رسوا اور مسمار ہوتے دیکھ کر علی گڑھ کا دیوانہ اپنے نوجوانوں کو اللہ اور انسانیت کی طرف لے بھاگے اور بھگا لے جانے پر آمادہ ہو جائے تو کیا کرے‘‘
(عزیزان علی گڑھ، ص۳۷)
’’عزیزان علی گڑھ‘‘ علی گڑھ کا قصہ پارینہ ہے، اس کے ماضی کی داستان ہے۔ اس کے ’فرزانوں کی…گمشدگی‘ کا نوحہ ہے۔ اور جس طرح اقبال سسلی کی بربادی پر روتے ہیں اور داغ دلی کی تباہی پر خون کے آنسو بہاتے ہیں اسی طرح رشید صاحب ماضی کے علی گڑھ کو یاد کر کے ’’آہ و فغان نیم شب‘‘ بلند کرتے ہیں۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو:
’’دیکھنے میں کالج چھوٹی سی بستی تھی لیکن اتنے بزرگوں، چھوٹے بڑے ساتھیوں اور ایسی امیدوں اور امکانات سے آباد معلوم ہوتی تھی جیسے علی گڑھ اپنے آباء و اسلاف اور اکابر کا خاندان اور وطن ہو، دن رات یگانگت کے تنوع اور تہنیت ہوں۔ رفتہ رفتہ یہاں تک محسوس ہونے لگا۔ جیسے علی گڑھ کی شہریت دنیا کی تمام مہذب اقوام اور ممالک کی شہرت کی ضامن ہو… زمانہ بدل گیا، طبیعتیں بدل گئیں اور ان کے ساتھ کیا کیا نہیں بدل گیا۔ غم اتنا بدل جانے کا نہیں جتنا مسخ ہو جانے کا ہے‘‘۔
(’’عزیزان علی گڑھ‘‘ ص۴۳ و ۴۴)
’عزیزان علی گڑھ‘ میں ماضی کے علی گڑھ کی بیشمار یادیں محفوظ کر دی گئیں ہیں ایم اے او کالج جہاں رشید صاحب نے ۱۹۱۵ء سے ۱۹۲۱تک تعلیم پائی، کی یاد اُن کے دل سے کبھی اوجھل نہیں ہوتی۔ وہ یہاں کی نہ صرف روایات اور اقدار کو یاد کرتے ہیں بلکہ بورڈنگ ہاؤس کا رہن سہن، ڈائننگ ہال، کلاس روم، مسجد، یونین کلب، کھیل کے میدان مشاعرے متعارفے حتی کہ ٹدرائڈ (کیچڑ پانی سے برسات کا خیر مقدم)کی یاد بھی ان کے دل کو کچو کے دیتی ہے۔
ماضی کے علی گڑھ سے سرسید احمد خاں، علی گڑھ تحریک اور بعدہٗ مسلم یونیورسٹی کی تحریک کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ’’عزیزان علی گڑھ‘‘ میں سرسید اور ان کی تحریک کا بھی قدرے تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ رشید صاحب کے خیال میں ’’مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد سے اب تک مسلمانوں کو کسی شخص یا ادارے نے وہ ہمہ جہتی فائدہ اور دور رس فائدہ نہیں پہنچایا جو علی گڑھ نے پہنچایا۔ ‘‘ وہ ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ ’’علمائے کرام اور دوسرے حضرات از راہ حقیقت پسندی اس کا تصور فرمائیں کہ علی گڑھ موجود نہ ہوتا تو ہندوستان میں پچھلے سو سال میں ہم کہاں اور کس حال میں ہوتے‘‘۔ ایک جگہ تو انھوں نے یہ تک کہہ دیا کہ ’’سرسید نہ ہوتے … تو آج مسلمان کہیں کے نہ ہوتے‘‘۔ رشید صاحب علی گڑھ تحریک کو سرسید کا یاک ’’تاریخی انقلاب آفریں اور تعمیری کارنامہ‘‘ قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں ’’سرسید نے علی گڑھ تحریک کو بروئے کار لاکر … مایوس کن اور اندیشہ ناک حالات پر قابو پانے کی کامیاب کوشش کی‘‘۔
مسلم یونیورسٹی کی تحریک کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ’’علی گڑھ جن شرائط پر قائم ہوئی، چنانچہ ان کے خیال میں ’’مسلمانوں نے اپنے خواب کی یونیورسٹی کو خیر آباد کہہ کر حقیقت یا بیداری کی پونیورسٹی کو وقت کا تقاضا سمجھ کر قبول کر لیا‘‘۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم یونیورسٹی اگر چہ ’’بدیسی حکومت‘‘ کے زیر سایہ وجود میں آئی تھی لیکن اسے وہ ’’حقوق و اختیارات‘‘ تفویض کیے گیے تھے جو اس کے ’’علمی، مذہبی اور اقلیتی کردار کی سلامتی‘‘ کے ضامن تھے اور اس کی ’’قدرتی نشو نما‘‘ میں معاون تھے۔ تقریباً تیس(۳۰) سال تک مسلم یونیورسٹی انھیں خطوط پر چلتی رہی اور بقول رشید صاحب اس نے ’’یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنی ذمہ داری اور اپنی ضروریات کا پورے طور پر احساس رکھتی تھی اور ان سے عہدہ برآمد ہونے میں حکومت وقت، اصحاب علم و فن اور ملک و ملت کے بہترین توقعات کو بہ طریق احسن پورا کر سکتی تھی۔ نیز ایک تہذیبی ادارے اور معیاری دانش کدہ کی حیثیت سے ہر حلقہ اور ہرسطح پر ممتاز منفرد تھی‘‘۔ لیکن آزادی کے بعد ۱۹۵۱ء میں جو یونیورسٹی ایکٹ پاس ہوا اس سے رشید صاحب بے حد ملول ہوئے کیوں کہ اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں کر دی گئیں تھیں جو اس کے ’’خصوصی کردار‘‘سے متناقض تھیں۔ علی گڑھ پر جب بھی کوئی ضرب پڑی تو رشید صاحب کا دل بری طرح دکھا۔ ۱۹۷۲ء میں جب مسلم یونیورسٹی ترمیمی بل پاس ہوا تو رشید صاحب کی بیحد تکلیف پہنچی۔ انھیں ایسا لگا جیسے کہ یہ یونیورسٹی اپنی نہ رہ گئی ہو، لیکن جب اس بل میں ’’اصلاح و رعایات و حقوق ‘‘ کا سامان کر دیا گیا تو انھوں نے اطمینان کا سانس لیا۔
رشید صاحب کی نظر میں ’’علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آزاد ہندوستان میں ملک کی سب سے اہم اور سب سے بڑی اقلیت کی یونیورسٹی ہے۔ سیکولر جمہوریہ میں اس کے خصوصی امتیازات اور حقوق کو برقرار رکھنے کی کا مسئلہ معمولی نہیں ہے‘‘۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ مسلم اقلیت کی یونیورسٹی ہے تو اسے اردو یونیورسٹی کی شکل میں کیوں فروغ نہیں دیا گیا۔ بعض لوگوں نے اس کے لیے سرسید کو مورد الزام قرار دیا ہے۔ کہ انھوں نے اردو کے بارے میں غلط پالیسی اختیار کی۔ رشید صاحب کا اس بارے میں موقف بالکل واضح ہے۔ اُن کے خیال میں ’’ مسلم یونیورسٹی کو اردو یونیورسٹی قرار دینے سے مسلمان ان فوائد سے محروم رہ جاتے جو انگریزی حکومت میں چھوٹی بڑی ملازمتوں کے ملنے اور مغربی علوم و فنون سے کامل شناسائی اور مغربی طور طریقوں کو اختیار کرنے سے میسر آسکتے تھے اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب مدرستہ العلوم اور مسلم یونیورسٹی انگریزی زبان اور مغربی علوم میں دسترس رکھنے میں معاصر یونیورسٹیوں سے بھی آگے ہوتی ‘‘۔ سرسید ابتدا میں مدرستہ العلوم (ایم اے او کالج) میں اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کے حق میں تھے، لیکن بعد میں وہ اپنے اس ارادے سے ہٹ گئے۔ رشید صاحب نے سرسید سے اتفاق کرتے ہوئے ان کے اس فیصلے کو ’’دور اندیشی اور حقیقت پسندی‘‘ سے تعبیر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :
’’سرسید کی بے بے مثل دوراندیشی اور حقیقت پسندی کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ انھوں نے اردو کے بارے میں اپنی رائے بدل دی اور علی گڑھ کو اردو ادارہ رکھنے کی بجائے اس کو ایک اعلیٰ درجہ کے انگریزی (مغربی) ادارے میں ڈھال دیا‘‘۔
(’’عزیزان علی گڑھ‘‘ ص۷۱)
رشید صاحب اردو یونیورسٹی کے قیام کے حق میں نہ تھے۔ ارباب نظم و نسق نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو اردو یونیورسٹی قرار نہ دے کر اُن کے خیال میں اچھا ہی کیا۔ کیوں کہ بقول اُن کے ’’اردو یونیورسٹی ہونے کی وجہ سے علی گڑھ کا وہی حشر ہوتا جو اردو کا ہوا‘‘۔ رشید صاحب اردو یونیورسٹی کو اردو سے الگ کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں جب تک کہ اردو کو وہ سہولیتں میسر نہ ہوں (مثلاً اردو کا علاقائی زبان ہونا) اس وقت اردو یونیورسٹی ’’کارآمد و کامیاب‘‘ نہیں ہوسکتی مسلم یونیورسٹی اردو یونیورسٹی کیوں نہ بن سکی۔ اس کی ایک اور وجہ رشید صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ’’ایم اے او کالج اور مسلم یونیورسٹی کی حیثیت ایک کل ہند ادارے کی تھی۔ اس میں ایسے طلبہ کو سبھی داخلے کا حق تھا جو ملک کے دور افتادہ حصول کے باشندے تھے اور ان کی مادری زبان اردو نہ تھی۔ اس بنا پر علی گڑھ کو ’’اردو برادر‘‘ رکھتے میں ہر طرف سے اور ہر طرح کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہی نہیں یقین تھا۔ اس لیے علی گڑھ کے لیے لازم تھا کہ وہ اس طرح کے پر خطر امکانات سے اپنے آپ کو علاحدہ اور محفوظ رکھے‘‘۔ لیکن اردو یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں سب سے بڑا ڈر انھیں مسلم یونیورسٹی کے مخالفین سے تھا۔ علاوہ ازیں حیدرآباد کی اردو یونیورسٹی (جامعہ عثمانیہ) کا جو حشر ہوا وہ بھی اُن کے پیش نظر تھا۔ اس ضمن میں ’’عزیزان علی گڑھ‘‘ کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو:
’’اگر مسلمان کی مغربی طرز کی اعلیٰ تعلیم گاہیں ملک کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوتیں … تو کسی ایک اردو کالج یا یونیورسٹی بنا دینے میں کوئی مضائقہ نہ تھا۔ لیکن لے دے کے صرف ایک علی گڑھ میں دوسرے عناصر کی آمیزش کی گئی ہوتی یا عوامل کو دخل دیا گیا ہوتا تو اس کے مخالف اس کے رسوا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ساری تعمیر مسمار ہو جاتی اور ہم شاید کہیں کہ نہ رہ جاتے۔ ۱۹۴۷ء تک انگریزی کے سوا ایک بھی دوسری زبان کی یونیورسٹی قائم کرنے کا مطالبہ کہیں سے نہیں کیا گیا اور جس زبان کی ایک جیتی جاگتی یونیورسٹی قائم تھی اس کا کیا حشر ہوا اور کیوں ہوا وہ بھی کوئی راز نہیں ہے‘‘۔
’’عزیزان علی گڑھ‘‘ میں اردو زبان کا ذکر بھی قدرے تفصیل سے ملتا ہے۔ اردو کے شاندار ماضی سے لے کر اس کی موجودہ صورت حال اور کس مپرسی تک کے تمام مراحل کو انھوں نے بخوبی بیان کیا ہے۔ رشید صاحب کا یہ قول بجا ہے کہ ’’ہندوستان کے بیشتر مسلمانوں کی مادری زبان اردو ہے۔ بہت بڑی تعداد ایسے غیر مسلموں کی ہے جو اس کو اس طرح کام میں لاتے ہیں جس طرح مسلمان‘‘ رشید صاحب نے اس حقیقت کا بھی برملا اظہار کیا ہے کہ ’’اردو کے جتنے مخلص اور دلیر حامی غیر مسلموں میں ملتے ہیں اتنے مسلمانوں کے کسی اور مطالبے کی تائید کرنے والے غیر مسلموں میں نہیں ملیں گے۔ لیکن ان کے خیال میں ’’یہ عجیب بات نہیں ہے کہ جتنی یہ کہ بعض مسلم شعراء اور ادیب اردو کی عمارت میں رخنے ڈالنے لگے ہیں۔ رشید صاحب کے خیال میں ‘‘ اردو کو اس لیے گردن زدنی قرار دینا کہ وہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے قرین انصاف نہیں ہے‘‘ تقسیم ملک کے بعد اردو پر جو بیتی اس کا کرب رشید صاحب نے یوں محسوس کیا:
’’تقسیم ملک کے بعد اردو دشمنی کی جو لہر اٹھی اُس کی وسعت اور شدت بڑھتی ہی گئی۔ سیاست اور حکومت کے سربراہوں سے سوا طفل تسلی اور نا معتبر وعدوں کے کچھ اور ہاتھ نہ آیا۔ پانی سرسے گذر گیا۔ جن بچوں کی مادری زبان اردو تھی وہ برابر اس سے محروم ہوتے گئے چنانچہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ روزی اور بے روزگاری کی خاطر اب خود اردو والے اردو سیکھنے پڑھنے سے احتراز کرنے لگے ہیں ‘‘۔
(’’عزیزان علی گڑھ‘‘ ص ۶۴)
اردو ہندی تنازعے کا ذکر کرتے ہوئے رشید صاحب لکھتے ہیں کہ ’’اردو ہندی کا مرض یا فتنہ کم و بیش پونے دو سو سال پرانا ہے، اور جیسا کہ بعض امراض کا خاصہ ہے کہ اگر وہ جلد دور نہ کیے جائیں تو ان کا ازالہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اردو کا حال کچھ اس طرح کا ہو کر رہ گیا ہے‘‘۔ اردو رسم خط بدلنے کی تحریک کو وہ ایک ’’رخنہ ‘‘اور ’’فتنہ‘‘ قرار دیتے ہیں۔
’’عزیزان علی گڑھ‘‘ کا معتدبہ حصہ شعراء کے تنقیدی تذکروں پر مشتمل ہے جن میں غالبؔ، حالیؔ، اقبالؔ اور اکبرؔالٰہ آبادی خصوصیت کے ساتھ قاب ذکر ہیں۔ ان شعراء کے کلام پر رشید صاحب کی تنقیدی آراء کو ہم تاثراتی (Impressionistic Criticiem) کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں رشید صاحب نقاد نہ تھے اور نہ ہی انھوں نے کبھی نقاد ہونے کا دعویٰ کیا، کیوں کہ ان کا اصل میدان تو طنز و مزاح انشائیہ نگاری اور خاکہ نگاری تھا جس میں انھوں نے اپنی شگفتہ مزاجی، بذلہ سنجی، شوخی، طبع اور ندرت بیان کے خوب خوب جوہر دکھائے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا فارسی اور اردو کے کلا کی شعراء کا مطالعہ بہت گہرا تھا۔ رشید صاحب کے ’’نقد پاروں، کو پڑھ کر اُن کے ہاں کسی ٹھوس تنقیدی نظریے کا سراغ تو نہیں لگایا جا سکتا لیکن اُن کی گہری تنقیدی بصیرت کا اندازہ ضرور ہوتا ہے۔ تاثراتی تنقید میں اختلاف رائے کی بہت کچھ گنجائش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رشید صاحب نے غالبؔ، حالیؔ، اقبالؔ اور اکبرؔ الٰہ آبادی کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس سے بہت کچھ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔
اس امر کا ذکر بیجا نہ ہو گا کہ رشید صاحب تنقید کے معاملے میں تعریف توصیف کے زیادہ قائل ہیں۔ اُن کی نظر فن پارے کی خامیوں سے زیادہ اس کی خوبیوں پر ہوتی ہے۔ وہ ادیب یا شاعر کی بڑی سے بڑی لغزش کو بھی نظر انداز کر جاتے ہیں اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی خوبی کی سبھی دل کھول کر داد دیتے ہیں۔ انھوں نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ’’میں تنقید میں میانہ روی کا قائل ہوں ‘‘۔ لیکن خود ان کی تنقید میں ’’میانہ روی‘‘ کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ان کی تنقیدی کاوشوں کو یک طرفہ تنقید کہنا زیادہ مناسب ہو گا کیوں کہ وہ صرف حسن کو دیکھتے ہیں قبیح کو نہیں، خوب کو دیکھتے ہیں زشت کو نہیں۔ بلکہ کبھی کبھی تو وہ زشت کو بھی خوب اور قبیح کو بھی حسن بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اکبرؔ الٰہ آبادی نے سرسید اور علی گڑھ پر جو لعن طعن کی ہے رشید صاحب اس میں بھی ’’خلوص‘‘ کی جھلک دیکھتے ہیں۔ اسی طرح حالیؔ کی تعریف کرتے ہوئے انھوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اقبال کے ’’کلام و پیام‘‘ کو جو اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی اس کے پیچھے حالیؔ کا ہاتھ تھا۔ حالیؔ کے کلام کی انھوں بے شمار خوبیاں بیان کی ہیں لیکن عقلیت اور واقفیت پسندی کا جو عنصر حالیؔ کے ہاں بدرجہ اتم موجود ہے، اس کا رشید صاحب نے کہیں ذکر نہیں کیا۔ اقبالؔ پر رشید صاحب کی جو تنقید ہے اس میں انھوں نے زیادہ تر ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جو وقتاً فوقتاً ان پر کیے جاتے رہے لیکن یہاں بھی معاملہ یک طرفہ ہے۔
چونکہ ’’عزیزان علی گڑھ‘‘ کے مخاطب طلبہ تھے، اس لیے رشید صاحب نے آخر میں طالب علمانہ زندگی سے متعلق سبھی چند باتیں کہیں ہیں۔ رشید صاحب چاہتے تھے۔ کہ طلبا میں علی گڑھ کی دیرینہ اور اعلیٰ روایات کا پاس ہو، وہ ڈسپلن کی پابندی کریں، تخریبی تحریکوں سے دور رہیں، سیاست میں حصہ نہ لیں، اپنے اندر اخلاقی پاکیزگی پیدا کریں، تعلیمی ذمہ داریوں کی طرف سے غفلت نہ برتیں، مسلمہ اخلاقی اقدار کو نظر انداز نہ کریں، سلیقہ اور خوش دلی کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اقامتی زندگی کی صالح تفریحی سرگرمیوں اور دیگر صحت مند مشاغل میں حصہ لیں اور ’’وہ کریں جو تعلیم، تہذیب اور اخلاق کا تقاضا ہو اور وہ نہ کریں جس کا مطالبہ سوجھ بوجھ سے بے گانہ جم غفیر کرتا ہو‘‘۔
خطبۂ ’’عزیزان علی گڑھ‘‘ انھیں ناصحانہ باتوں پر ختم ہو جاتا ہے۔
٭٭٭
فیضؔ کی نظم’ تنہائی‘
(ایک اسلوبیاتی مطالعہ)
’اسلوبیات‘(Stylistics)نسبتہً ایک جدید نظریۂ تنقید ہے۔ ادبی فن پارے کی تنقید و تشریح اور تحلیل و تجزیے کے طریقوں میں گذشتہ صدی کے دوران نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ روایتی طرزِ تنقید کی رو سے ادبی نقاد مصنف کے حوالے کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا تھا۔ لیکن بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں روسی ہیئت پسندی کے ارتقا اور اُسی زمانے میں فرانس میں فرڈی نینڈڈی سسیور کے انقلاب آفریں لسانی افکار نے، جن سے ساختیات کے سوتے پھوٹے، ادبی تنقید کی کایا ہی پلٹ دی۔ نقاد کی توجہ اب مصنف کے بجائے ادبی فن پارے یا متن پر مرتکز ہونے لگی۔ آگے چل کر رولاں بارت نے ’مصنف کی موت‘ کا اعلان بھی کر دیا۔ اسلوبیاتی نظریۂ تنقید روسی ہئیت پسندی، عملی تنقید، نئی تنقید، اور ساختیاتی وپس ساختیاتی تنقید ہی کی طرح ’متن اساس‘تنقید ہے جس میں تاریخی اور سوانحی حوالوں سے صرفِ نظر کرتے ہوئے صر ف ادبی متن کے مطالعے اور تجزیے سے سروکار رکھا جاتا ہے۔ روایتی ادبی تنقید میں نقاد اپنا سارا زور ادبی فن پارے کی تشریح (Interpretation) اور اس کی خوبی یا خامی بیان کرنے میں صرف کر دیتا ہے۔ اُس کا انداز داخلی اور تاثراتی ہوتا ہے۔ اس کے علی الرغم اسلوبیاتی تنقید ادبی متن کی توضیح (Description) اور اُس کے اسلوبی خصائص (Style-features)کو نشان زد کرنا اپنا بنیادی مقصد قرار دیتی ہے۔ اس کا انداز معروضی اور تجزیاتی ہوتا ہے۔
اس امر کا ذکر یہاں بے جا نہ ہو گا کہ اسلوبیات، اطلاقی لسانیات کی ایک شاخ ہے۔ اس لیے اس میں لسانیاتی طریقِ کار اور لسانیاتی حربوں سے خاطر خواہ مدد لی جاتی ہے، اور لسانیات کی تمام سطحوں یعنی صوتی، صرفی لغوی، قواعدی، نحوی اور معنیاتی سطحوں پر ادبی متن کی تحلیل و تجزیے کا کام سرانجام دیا جاتا ہے۔
اس مقالے میں فیض احمد فیضؔ کی نظم ’’تنہائی‘‘ کا اسلوبیاتی تجزیہ صرفی و لغوی سطح پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فیض کی یہ ایک مختصر سی نظم ہے جو اُن کے پہلے مجموعۂ کلام ’نقشِ فریادی‘(۱۹۴۱ء)‘ میں شامل ہے۔ اس نظم میں کل نو مصرعے ہیں۔ اس کی قرأت یوں ہے:
پھر کوئی آیا دلِ زار ! نہیں، کوئی نہیں
راہ رو ہو گا کہیں اور چلا جائے گا
ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار
لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ
سو گئی راستہ تک تک کے ہر اک راہ گذار
اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ
گل کرو شمعیں بڑھا دو مے و مینا و ایاغ
اپنے بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو
اب یہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں آئے گا
جیسا کہ ظاہر ہے اس نظم میں رات کی منظر کشی کی گئی ہے، شاعر تنہا ہے، اُسے کسی کا شدت سے انتظار ہے، انتظار کی گھڑیاں طویل تر ہوتی جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ شاعر کی مایوسی، اداسی، اور افسردگی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اردو شعر و ادب میں تنہائی کوئی نیا موزوں نہیں، لیکن فیض کے اسلوبِ بیان اور طرزِ اظہار نے اس نظم کو ایک شاہکار ادبی تخلیق بنا دیا ہے۔
جب ہم اس نظم کے لفظی سرمایے پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری توجہ لغوی ربط و اتصال (Lexical Cohesion)پر مرکوز ہوتی ہے۔ الفاظ کی سطح پر اسلوب کی یہ وہ خصوصیت ہے جس میں کسی ادبی فن پارے کے دو یا دو سے زیادہ الفاظ باہم مربوط (Cohesive)ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ربط، علاقہ یا نسبت رکھتے ہیں۔ زیرِ تجزیہ نظم میں وقوع پذیر ایسے الفاظ کے حسبِ ذیل پانچ زمرے قائم کیے جا سکتے ہیں ـ:
۱- رات، تاروں، شمعیں، چراغ، خوابیدہ، سو گئی۔
۲- راہ رو، راستہ، راہ گذار۔
۳- مے، مینا، ایاغ۔
۴- غبار، خاک۔
۵- کواڑوں، مقفل۔
اس تجزیے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے زمرے میں دوسرے تمام زمروں سے زیادہ الفاظ شامل ہیں، چنانچہ یہ زمرہ بنیادی زمرہ کہلائے گا۔ اس زمرے کا کلیدی لفظ ’رات‘ ہے۔ اس زمرے کے دوسرے الفاظ یعنی تارے، چراغ، شمعیں، خوابیدہ اور سو گئی کلیدی لفظ ’رات‘ سے مناسبت رکھتے ہیں۔ ’رات‘ اور اس سے مناسبت رکھنے والے تمام الفاظ جن کا تعلق زمرۂ اول یا بنیادی زمرے سے ہے، نظم کا Surface structure یعنی خارجی ڈھانچا فراہم کرتے ہیں جو نظم کا بنیادی ڈھانچا ہے۔
’خارج‘ ہی سے ہم ’داخل‘ کی جانب رجوع کرتے ہیں جو اس نظم کا Deep structureہے، جہاں شاعر کے دل کی اداسی اور افسردگی ہمارے دامنِ دل کو کھینچتی ہے۔ رات کا دل کی افسردگی سے گہرا تعلق ہے۔ میرؔ کا دل تو شام ہی سے بجھا سا رہنے لگتا تھا۔ فیض کا دل اُس وقت بجھتا ہے جب رات ڈھل چکی ہوتی ہے، تاروں کا غبار بکھرنے لگتا ہے، راہیں سونی ہو جاتی ہیں، اور کسی کے قدموں کی آہٹ کے امکانات معدوم ہو جاتے ہیں۔ مایوسی اور ناامیدی کی اس گھڑی میں شاعر کا دل دنیا کی ہر چیزسے اچاٹ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سامانِ عیش و نشاط بھی اُسے خوش نہیں آتے، چنانچہ وہ قدرے جھنجلا کر کہتا ہے:
گل کرو شمعیں بڑھا دو مے و مینا و ایاغ
اپنے بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو
کیوں کہ اسے اس بات کا پورا یقین ہو چکا ہے کہ، ع
اب یہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں آئے گا
زیرِ تجزیہ نظم میں Lexical Cohesionکے علاوہ Semantic Cohesion، یعنی معنیاتی ربط و اتصال کی بھی عمدہ مثالیں پائی جاتی ہیں۔ زمرۂ اول یعنی بنیادی زمرے کے بیشتر الفاظ کے ساتھ فیض نے جو فعلی شکلیں استعمال کی ہیں ان میں معنیاتی ربط و اتصال کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ جب ہم ان تراکیب پر غور کرتے ہیں، مثلاً رات کا ڈھلنا، تاروں کا بکھرنا، چراغ کا لڑکھڑانا، شمع کا گل ہونا، چراغ کا خوابیدہ ہو جانا، راہ گذار کا سو جانا تو ہمیں ڈھلنا، بکھرنا، لڑکھڑانا، گل ہونا، خوابیدہ ہونا اور سوجانا جیسے مصادر میں معنی کی صرف ایک ہی رَو دوڑتی ہوتی نظر آتی ہے اور وہ ہے زوال پذیری کی رو جسے امید و نشاط کے خاتمے اور مایوسانہ طرزِ احساس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، چنانچہ رات، تارے، شمع، چراغ، راہ گذار سبھی مظاہر زوال خوردہ نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رات کا ڈھلنا، تاروں کا بکھرنا، چراغ کا لڑکھڑانا، شمع کا گل ہونا، وغیرہ کو فیض نے نظم میں شعری علائم کے طور پر برتا ہے۔ فرڈی نینڈ ڈی سسیور کی لسانیاتی اصطلاح میں یہ علائم Signifiersکا درجہ رکھتے ہیں جن کا Signified زوال پذیری کا عمل ہے جو ایک حالت یا کیفیت (State) کا نام ہے جس کا گہرا تعلق ذہنی کیفیت (State of mind)سے ہے۔ یاس و افسردگی، اداسی اور دل گیری اِسی ذہنی کیفیت کی ایک شکل ہے جو عالمِ تنہائی میں شدید تر ہو جاتی ہے، اور جس کا اظہار شاعر نے نظم کی ابتدا ہی میں ’’دلِ زار ‘‘ کی ترکیب استعمال کر کے کر دیا ہے۔ نظم ایک ڈرامائی انداز سے شروع ہوتی ہے، لیکن ’’نہیں ‘‘ کی تکرار سے منظر اچانک تبدیل ہو جاتا ہے، ع
پھر کوئی آیا دلِ زار! نہیں، کوئی نہیں
اور اسی ’’نہیں ‘‘ کی دوبارہ تکرار سے نظم اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، ع
اب یہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں آئے گا
’’نہیں ‘‘ جو حرفِ تنکیر ہے نظم میں محرومی کا اشاریہ بن جاتا ہے اور اِس کی تکرار محرومی کے احساس کو شدید تر کر دیتی ہے۔
الفاظ کی سطح پر اس نظم کا تجزیہ کرتے وقت اسلوبیاتِ فیض کی ایک اور خصوصیت کی جانب ہماری توجہ مبذول ہوتی ہے جسے لسانیاتی اصطلاح میں ’فور گراؤنڈنگ‘ (Foregrounding) کہتے ہیں جس سے مراد الفاظ و تراکیب کا وہ نادر اور انوکھا استعمال ہے جو زبان کے عام استعمال یا معمول (Norn) سے ہٹ کر ہوتا ہے اور جو ہماری توجہ فوراً اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ فور گراؤنڈنگ میں زبان کا عام استعمال پس منظر میں چلا جاتا ہے جس کی جانب ہماری کوئی خاص توجہ مبذول نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں زبان کا مخصوص و منفرد اور نادر استعمال پیش منظر میں آ کر کشش کا باعث بنتا ہے۔ فورگراؤنڈنگ کی اصطلاح سب سے پہلے لسانیات کے پراگ اسکول کے ایک ممتاز نقاد اور ماہرِ اسلوبیات مکار و وسکی نے عام زبان اور شاعری کی زبان میں فرق بتلانے کے لیے استعمال کی تھی۔ اس سے اُس کی مراد الفاظ کے غیر عقلی انسلاکات(Illogical combinations)سے تھی جن سے شعری زبان میں تنوع، ندرت اور انوکھا پن پیدا ہوتا ہے اور زبان کے تخلیقی استعمال کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ اُس کا قول ہے کہ’’ شاعری کی زبان کو لازماً فور گراؤنڈڈ ہونا چاہیے‘‘۔ (The language of poetry must be foregrounded)
فیضؔ نے اپنی نظم ’’تنہائی‘‘ میں بعض ایسی نادر تراکیب و انسلاکات اور Expressions استعمال کیے ہیں جو ہماری توجہ فوراً اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں،
مثلاً:
۱- خوابیدہ چراغ۔
۲- بے خواب کواڑ۔
۳- چراغوں کا لڑکھڑانا۔
۴- راہ گذار کا سوجانا۔
۵- راہ گذار کا راستہ تکنا۔
۶- اجنبی خاک۔
۷- اجنبی خاک کا قدموں کے سراغ کو دھند لا دینا۔
ان مثالوں میں شاعر نے ذی روح (Animate) کو غیر ذی روح (Inanimate) کے ساتھ منسلک کر کے غیر عقلی انسلاکات (Illogical combinations)تخلیق کیے ہیں۔ فارسی مصدر خوابیدن یعنی ’سونا‘ ایک جبلی عمل ہے جو صرف ذی روح سے متصف ہے، مثلاً:
سَرھانے میرؔ کے آہستہ بولو
ابھی ٹک روتے روتے سوگیا ہے
لیکن فیضؔ نے غیر ذی روح اشیا، مثلاً چراغ کے ساتھ خوابیدہ، کواڑوں کے ساتھ بے خواب اور راہ گذار کے ساتھ سو گئی کے انسلاک سے اظہار میں جدت، ندرت، تنوع اور تازگی پیدا کی ہے، اور اظہار کا یہی انوکھا انداز ہمارے دامنِ دل کو اپنی جانب کھینچتا ہے جسے لسانیاتی اصطلاح میں ’فورگراؤنڈنگ‘ کہتے ہیں۔ اِسی طرح چراغ کا لڑکھڑانا، راہ گذار کا راستہ تکنا، خاک کا اجنبی ہونا، اور اجنبی خاک کا قدموں کے سراغ کو دھندلا دینا جیسے اظہار ات (Expressions) بھی فورگراؤنڈنگ کی حدوں کو چھوتے ہیں۔
اردو کے بعض ناقدین نے فیضؔ پر اپنی تحریروں میں اُن کی نظم ’’تنہائی‘‘ کا بہ طورِ خاص ذکر کیا ہے، لیکن انھیں اس نظم میں پراسراریت اور رومانیت کے وجود اور رجائیت کے عدم وجود کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آیا، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظم فیضؔ کے شعری اور تخلیقی اظہار کا ایک بہترین نمونہ ہے۔
(لانگ آئی لینڈ [نیویارک] میں منعقدہ سہ روزہ بین الاقوامی فیض صدی تقریبات میں جون ۲۰۱۱ء میں پڑھا گیا)۔
٭٭٭
تا نیثیت
دنیا میں انسانی مساوات کے قیام کی خواہش قوموں کے دلوں میں اکثر پیدا ہوتی رہی ہے۔ اسی کی ایک نمایاں شکل عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق تفویض کیے جانے کی جدوجہد ہے جس نے مغرب میں انیسویں صدی کے دوران ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ حقوقِ نسواں کی اس تحریک کو ’تانیثیت‘ (Feminism) کا نام دیا گیا۔ یہ تحریک ان عورتوں نے شروع کی تھی جو سیاسی، سماجی اور معاشی نا برابری کے زخم کو خود سہہ چکی تھیں۔ بعد میں عورتیں اور مرد دونوں اس تحریک میں پیش پیش رہے جنھیں ’تانیثیت پسند‘ (Feminists)کہا گیا۔ انھی میں کچھ ایسے مفکرین بھی پیدا ہوئے جنھوں نے تانیثیت کے نظری ڈسکورس میں حصہ لیا، اور فلسفیانہ طور پر اس کے اِشوز اور مسائل سے بحث کی جس سے تانیثی تھیوری کی تشکیل عمل میں آئی۔
(۲)
کہا جاتا ہے کہ مرد کی تخلیق عورت کی تخلیق سے پہلے عمل میں آئی، لیکن ’’خلد‘‘ سے نکلنے کے بعد مرد اور عورت دونوں روئے زمین پر ازل سے ایک ہی ساتھ رہتے آئے ہیں۔ اس قربت، موانست اور رفاقت کی بنیادی وجہ ان دونوں کے درمیان حیاتیاتی (بائیلوجیکل) تفریق تھی۔ اسی تفریق کی بنا پر عورت قرن ہا قرن سے جنسی و تولیدی عمل سے گذرتی رہی ہے۔ مرد تولیدی عمل کا سبب تو بنتا ہے، لیکن اسے شئیر نہیں کرتا۔ اس عمل کا سارا بار عورت ہی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے عورت، بہ مقابلۂ مرد، کم زور اور نازک و ناتواں سمجھی جاتی ہے، اور جذباتی سطح پر وہ زیادہ حساس اور نم دیدہ (Prone to tears)واقع ہوئی ہے۔ (۱) عورت کو ’’ناقص العقل‘‘ بھی کہا گیا ہے(اگر چہ سائنس اسے ثابت نہیں کر سکی ہے)۔ اس کے علی الرغم مرد عقل و فراست، ذہانت اور تفکر پسندی کی صفت سے متصف قرار دیا گیا ہے۔
اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سماجی و معاشرتی سطح پر عورت کے ساتھ بے شمار زیادتیاں اور نا انصافیاں ہوتی رہی ہیں۔ خانگی تشدد، زد و کوب، جنسی استحصال، ریپ(اکثر ریپ کے بعد قتل )، اور بعض ملکوں میں جہیزی اموات چند ایسے واقعات ہیں جو عورت کے ساتھ آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ عورتوں کو سماجی نا برابری اور جینڈر تفریق (سماجی اور تہذیبی سطح پر جنسی تفریق)کے کرب سے بھی گذر نا پڑتا ہے۔ سماجی و سیاسی سطح پر بعض حقوق جو مردوں کو حاصل ہیں وہ عورتوں کو حاصل نہیں، مثلاً کئی ملکوں میں آج بھی عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ادب اور آرٹ میں عورتوں کو ’’سامان‘‘ یا کموڈٹی، بلکہ سیکس کموڈٹی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اجنتا، ایلورا اور کھجوراہو کے غاروں کے سنگ تراشی کے نمونے ہوں یا دنیا کے عظیم مصوروں کے فنی شاہکار یا عالمی ادب کے شعری متون، ہر سطح پر عورت کے جنسی پیکر و تمثال(Images) اور جنسی حوالے موجود ہیں جو احساسِ حسن و جمال پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جنسی جذبے کو بھی متحرک اور بیدار کر دیتے ہیں۔ سنسکرت کی ’’شرنگاررس‘‘کی شاعری کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ یہ فرد کے جنسی جذبے کو بیدار کرتی ہے۔ (۲)
اقبالؔ نے فنونِ لطیفہ کی اس صورتِ حال پر یوں اظہارِ افسوس کیا ہے ؎
ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس
آہ بے چاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار
سماج نے عورت کو بیوی کا درجہ تو دیا، لیکن اسی سماج نے ایسے حالات پیدا کیے کہ عورت کو ’’زنِ بازاری ‘‘ کا کردار بھی ادا کرنا پڑا، اور ’’داشتہ‘‘ بن کر بھی زندگی گزارنی پڑی جس سے اس کی معاشی بہتری تو ہوئی، ساتھ ہی اسے (اس کے خیال میں ) بیوی پر برتری بھی حاصل ہوئی۔ کسی نے مزاحیہ طرزِ اظہار کا سہارا لے کر اسی بات کو یوں کہا ہے، ع
زوجہ می آید بہ رکشہ، داشۃ آید بہ کار (۳)
کوئی شخص ’’کار‘‘ اسی وقت خرید سکتا ہے جب کہ اس کے پاس وافر رقم موجود ہو، اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ رقم اس کے پاس آئی کہاں سے ! جسم فروشی عورت کا ایک نہایت گھناؤنا روپ ہے، یہ اس کا اصلی روپ نہیں۔
(۳)
مغرب میں تانیثی جدوجہد کا آغاز اس وقت ہوا جب حقوقِ نسواں کے تحفظ کے لیے بعض عورتوں نے انفرادی طور پر آواز بلند کی۔ اس ضمن میں برطانیہ کی میری وول اسٹون کریفٹ (Mary Wollstonecraft)(۴) کا نام خصوصیت کے ساتھ قابلِ ذکر ہے جس نے اٹھارویں صدی کے نصفِ دوم میں سماجی سطح پر عورتوں اور مردوں کے درمیان نا برابری (جینڈر تفریق) کے خلاف نہایت پر زور انداز میں آواز اٹھائی اور حقوقِ نسواں کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کا موقف تھا کہ عورتیں طبعاً مردوں سے ’’کم تر‘‘ (Inferior)نہیں ہوتیں، لیکن وہ کم تر اس لیے سمجھی جاتی ہیں کہ ان میں تعلیم کی کمی پائی جاتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ عورتوں اور مردوں دونوں کو Rational beingsکے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ نا برابری کے خاتمے کے لیے وہ ایک ایسے سماجی نظم و ضبط (Social order) کی ضرورت کو محسوس کرتی تھی جو Reasonپر مبنی ہو۔ حقوقِ نسواں سے متعلق اس کی مشہور کتاب A Vindication of the Rights of Woman(1792) تانیثیت پسندوں کو آج بھی دعوتِ فکر دیتی ہے۔
میری وول اسٹون کریفٹ کے بعد حقوقِ نسواں کے تحفظ کے لیے منظم طور پر جدو جہد کا آغاز ہوا جس نے مغرب میں ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ اس تحریک میں اولاً عورتیں ہی پیش پیش رہیں، لیکن بعد میں مرد بھی اس میں شامل ہو گئے۔
تانیثی تحریک کا بنیادی مقصد عورتوں کو مردوں کے مساوی سیاسی، سماجی، معاشی اور قانونی حقوق دلانا تھا اور ترقی کے میدان میں انھیں برابر کے مواقع فراہم کرانا تھا۔ تانیثیت، اپنے عام مفہوم میں، صرف عورتوں ہی کے اِشوز کی ذمہ دار ہے اور جینڈر کے تعلق سے نا برابری کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ جیسے جیسے تانیثی تحریک فروغ پاتی گئی، اس کے نظر ی اور فلسفیانہ ڈسکورس میں بھی تبدیلی آتی گئی۔
تانیثی تھیوری ایک ایسے نظری ڈسکورس کا نام ہے جس میں فلسفیانہ طور پر نسائی اِشوز اور مسائل سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ تھیوری ان سماجی و سیاسی تحریکات سے اپنا رشتہ استوار کرتی ہے جو عورتوں کے حقوق کی پاس داری کرتی ہیں خواہ ان کا تعلق ازدواجی زندگی کے مسائل سے ہو یا سیاسی و معاشی معاملات سے، یا محض سماجی نابرابری اور جینڈر تفریق سے۔ (۵)
تانیثیت پسندوں (Feminists)نے عام زندگی میں عورت کی تذلیل و خواری، خانگی سطح پر اس کے ساتھ پیش آنے والے تشدد کے واقعات (Domestic violence)، شوہر کے ذریعہ اسے زد و کوب کیے جانے (Wife-beating) کی وارداتوں، نیز اس کے ساتھ جنسی زور زبردستی، جنسی استحصال اور آبرو ریزی کے خلاف بھی احتجاج کیا ہے۔ تانیثیت پسند معاشی سطح پر بھی عورتوں کے حقوق کی پاس داری کرتے ہیں اور ان کے لیے بہتر ورکنگ حالات و سہولیات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ عورتوں کے لیے کیریر کے مساوی مواقع اور مساوی مشاہرے کی حمایت کرنا بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ (۶)
(۴)
تانیثی مطالعات سے پتا چلتا ہے کہ مغرب میں تانیثیت کی تحریک نے اپنی ابتدا(انیسویں صدی) سے زمانۂ حال تک تین ارتقائی مراحل طے کیے جنھیں ’’لہروں ‘‘ (Waves)سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اجتماعی طور پر تانیثیت کی لہر اٹھنے سے پہلے حقوقِ نسواں کی تمام تر جدو جہد انفرادی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ اس وقت تک ’تانیثیت‘(Feminism) کی اصطلاح بھی رائج نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ان عورتوں نے، جنھوں نے حقوقِ نسواں کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی تھی، خود کو ’تانیثیت پسند‘(Feminist)کہا تھا۔ یہ دونوں اصطلاحیں تانیثی ادب میں کافی بعد میں مستعمل ہوئیں۔
پہلی تانیثی لہر برطانیہ میں انیسویں صدی کے وسط میں ابھری جب لندن کی متوسط طبقے کی خواتین نے بار براباڈ یکون (Barbra Bodichon)اور بیسی رینر پارکس (Bessie Rayner Parkes)کی سربراہی میں سماجی اور قانونی نا برابری، اور بے انصافی کے خلاف منظم طور پر آواز اٹھائی اور متحد ہو کر حقوقِ نسواں کا پرچم بلند کیا۔ اسی وقت سے تانیثی جدوجہد نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ یہ اس تحریک کی ’’پہلی لہر‘‘ تھی۔ اس لہر کے دوران تانیثیت پسندوں نے جن اِشوز پر اپنی توجہ مرتکز کی ان میں عورتوں کی تعلیم، ان کے لیے روز گار کے مواقع اور شادی سے متعلق قوانین تھے۔ ان تینوں میدانوں میں انھیں زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ عورتوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھل گئے، طب (Medicine) اور دوسرے پیشوں میں انھیں روزگار کے مواقع حاصل ہونے لگے، اور ۱۸۷۰ء کے ایکٹ (Married Women’s Property Act of 1870)کی رو سے شادی شدہ عورتوں کو حقِ ملکیت بھی حاصل ہو گیا۔ تانیثیت کی یہ پہلی لہر پہلی عالمی جنگ (۱۹۱۴تا۱۹۱۸ء) تک جاری رہی۔
تانیثی تحریک کی ’’دوسری لہر‘‘ نہ صرف برطانیہ، بلکہ دوسرے یورپی ممالک اور امریکہ تک پھیل گئی۔ بیسویں صدی کے دوران ان تمام ممالک میں عورتوں کے حقوق کی پاس داری کے لیے آواز اٹھائی گئی اور زبردست جدوجہد کا سلسلہ جاری رہا۔ نسلی بنیادوں پر تفریق کے خلاف بھی جدوجہد جاری رہی۔ لسبین (Lesbian)اِشوز اور اسقاطِ حمل کے حق کو بھی حقوقِ نسواں کی تحریک میں شامل کر لیا گیا۔ بعض جنسی و نسائی مسائل پر عدم اتفاقِ رائے کی وجہ سے دوسری تانیثی لہر تنازعات کا شکار ہو کر ۱۹۹۰ء کے آس پاس ختم ہو گئی۔
تانیثی تحریک کی ’’تیسری لہر‘‘ بیسویں صدی کے آخری دہے سے ذرا قبل نمودار ہوئی۔ اسے ’جدید تانیثیت‘ (Modern Feminism) بھی کہتے ہیں۔ یہ لہر دوسری تانیثی لہر کی ناکامی سے پیدا ہونے والی صورتِ حال کے تناظر میں معرضِ وجود میں آئی۔ اس تحریک سے نوجوان خواتین وابستہ ہوئیں جن کی عمریں ۳۰، ۳۵، یا ۴۰ سال سے زیادہ نہ تھیں۔ اس تحریک سے عورت کی ایک نئی شبیہ ابھر کر سامنے آئی۔ اب عورت ادعائیت کی حامل (Assertive)ہے، طاقت ور ہے اور اپنی جنسیت (Sexuality) پر اسے خود اختیار ہے۔ (۷) تیسری تانیثی لہر کے دوران اس بات کا بھی احساس پیدا ہوا کہ عورت کا تعلق مختلف رنگ، نسل، طبقے، قومیت، مذہب، اور تہذیبی و ثقافتی بیک گراؤنڈ سے ہوسکتا ہے۔ (۸) یہ تحریک یا لہر عورت کی معاشی، سیاسی اور سماجی مختاریت (Empowerment)کے ساتھ ساتھ اس کی انفرادی مختاریت پربھی اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اس تحریک کے دوران عورت کا تشخص (Identity)ابھر کر سامنے آگیا ہے۔ اکثر عورتیں متضاد تشخصات کی حامل ہوتی ہیں۔ بعض خواتین کیریر وومَن، بیوی، اور نیک لڑکی کا کردار نبھاتی ہیں تو بعض ٹام بوائے، لسبین اور سیکس سمبل کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں۔ یہ تحریک عورت کو اپنا تشخص یا پہچان خود قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔
(۵)
تانیثی تھیوری درحقیقت ان فلسفوں سے نمو پذیر ہوتی ہے جو تانیثیت کے مختلف نظری ڈسکورس کے پسِ پردہ ہیں، جیسے کہ سوشلسٹ فلسفۂ حیات جو ’سوشلسٹ تانیثیت‘ (جسے ’مارکسی تانیثیت‘ بھی کہتے ہیں ) کی روح ہے۔ اس فلسفے کی رو سے عورتوں کو برابری کا درجہ صرف اسی وقت مل سکتا ہے جب سماج میں بہت بڑے پیمانے پرکوئی تبدیلی واقع ہو۔ سوشلسٹ تانیثیت پسندوں کا کہنا ہے کہ نا برابری سرمایہ دارانہ سماج (Capitalist Society) میں بری طرح جڑ پکڑ چکی ہے جہاں قوت (Power)اور سرمایے (Capital)کی تقسیم غیر مساویانہ ہے۔ صرف یہی کافی نہیں کہ عورتیں انفرادی طور پر جدوجہد کر کے سماج میں اعلیٰ مقام حاصل کریں، بلکہ سماج میں اجتماعی تبدیلی (Collective Change)کی اشد ضرورت ہے تاکہ عورت اور مرد دونوں کو برابری کا درجہ حاصل ہوسکے۔ سوشلسٹ تانیثیت اسی لیے پدری سماجی نظام (Patriarchy)کی بھی مخالف ہے کہ یہ مردانہ اقتدار و قوت کی علامت ہے۔
’ریڈیکل تانیثیت‘سوشلسٹ تانیثی تھیوری سے کافی حد تک متاثر ہے۔ تانیثی مفکر ین جو ریڈیکل نظریات کے حامل ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی بڑی ڈرامائی سماجی تبدیلی کے بغیر عورتوں کو برابری کا درجہ نہیں مل سکتا، نیز عورتوں کی پستی (Oppression)کی بنیادی وجہ پدری نظام ہے جس میں اقتدار مرد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور عورت مجبورِ محض تصور کی جاتی ہے۔ مرد کا عورت پر تفوق قوت (Power)کے بل بوتے پر ہے۔ اسی لیے وہ آئے دن مردوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتی رہتی ہے۔ ریڈیکل تانیثیت پسندوں کا سارا ارتکاز اس ظلم و ستم پر ہے جو پدری نظام میں مرد عورت پر ڈھاتا ہے اور اپنے جابرانہ رویے سے اسے سماجی سطح پر زیر کر لیتا ہے اور پست (Oppressed)بنا دیتا ہے خواہ وہ امیر ہو یا غریب، گوری ہو یا کالی، تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ۔ اسی لیے ریڈیکل تانیثیت پدری نظام اور مردانہ اقتدار کے سخت خلاف ہے۔
سوشلسٹ تانیثی فکر کے علی الرغم ’لبرل تانیثیت‘ نا برابری کے خاتمے کے لیے اجتماعی سماجی تبدیلی کے بجائے انفرادی کوشش و عمل (Individualistic actions)کو ضروری قرار دیتی ہے۔ اس فلسفے کی رو سے عورتیں انفرادی طور پر کام اور جدو جہد کر کے سماج میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ اس حقیقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہت سے مغربی ملکوں میں عورتیں آج ان عہدوں پر فائز ہیں جو پہلے مردوں کی دسترس میں تھے۔ ہر چند کہ لبرل تانیثیت سیاسی و قانونی اصلاحات کے ذریعے مرد و زن میں برابری کی خواہاں ہے، تاہم اس کا ارتکاز عورتوں کی اپنی صلاحیتوں اور کوششوں پر ہے جنھیں بروئے عمل لا کر وہ سماج میں برابری کا درجہ حاصل کر سکتی ہیں۔
بعض یورپی ممالک (بالخصوص برطانیہ اور فرانس) نے جب تیسری دنیا کے ملکوں پر اپنا تسلط قائم کیا تو یہ ممالک ان کی کالونیاں (نو آباد بستیاں ) بن کر رہ گئے جس کی وجہ سے وہاں کی سیاسی اور معاشی صورتِ حال بالکل بدل گئی اور تانیثیت کی ایک نئی شکل ابھر کر سامنے آئی جسے ’مابعد نو آبادیاتی تانیثیت‘ کا نام دیا گیا۔ اسے تیسری دنیا کی تانیثیت یا تھرڈ ورلڈ تانیثیت بھی کہا گیا جس کے مفکرین کا خیال ہے کہ مغربی نوآباد کاروں نے تھرڈ ورلڈ ممالک کو سماجی و معاشی پستی کے غار میں دھکیل دیا ہے جس کی وجہ سے مابعد نوآبادیاتی معاشرے (Post-colonial society)میں عورت کی حیثیت فرد تر اور پست ہو کر رہ گئی ہے۔ مابعد نوآبادیاتی تانیثیت پسندوں نے مغربی نو آباد کاروں کی اندھی تقلید اور ان کی تہذیب اور طرزِ بود و باش کی بے جا نقالی اور تھرڈ ورلڈ ممالک کی عورتوں میں بڑھتی ہوئی مغربیت اور ماڈرنایزیشن کے مغربی معیارات پر بھی انگلی اٹھائی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عورتوں کا معیارِ زندگی محض مغربی تہذیب کی نقالی کر کے بلند نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے اپنے اپنے ممالک کی سماجی، ثقافتی اور تہذیبی قدروں سے ہم آہنگ کر کے بھی اونچا اٹھایا جا سکتا ہے۔
(۶)
یہاں اس امر کا ذکر بے جا نہ ہو گا کہ ’تانیثیت‘ اب صرف ایک مغربی اصطلاح نہیں رہی۔ تیسری دنیا کے ملکوں (بہ شمولِ ایشیائی ممالک) میں تانیثیت کا تصور اب بہت عام ہو چکا ہے۔ ہندوستان میں، جہاں مسلمانوں کا کثیر اجتماع پایا جاتا ہے ’اسلامی تانیثیت‘ (Islamic Feminism)کی اصطلاح رائج ہو چکی ہے۔ یہاں کی پڑھی لکھی مسلم خواتین اب نہایت سنجیدگی سے اس بات کو سوچنے لگی ہیں کہ انھیں سماج میں مردوں کے مساوی حقوق ملنے چاہییں۔ عذرا بانو نے، جو لکھنؤ کے ناری شکشا نکیتن میں اقتصادیات کی ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں، اس موضوع پر نہایت جرأت مندی سے قلم اٹھایا ہے۔ وہ لکھتی ہیں :
’’جنسی مساوات ایک طرح کی جنگ نہیں مردوں سے، بلکہ ایک ایسی روایت کو توڑنا ہے جو ہمارے سماج میں برسوں سے بودی گئی ہے۔ سماج کو چاہیے کہ اس کی اہمیت کو محسوس کریں اور قبول کریں کہ عورت اور مرد زندگی کے ہم سفر ہیں، اور سماج کی پہچان اور ترقی صرف مردوں سے نہیں، بلکہ عورتوں سے بھی ہوتی ہے۔ ۔ ۔ آج کی عورت نے برابری کی آواز اٹھانے کے حق کو طلب کیا ہے۔ یہ برابری تعلیم، نوکری، سیاست، اور جائداد وغیرہ کے لیے ہے۔ یہ نعرے عورتوں کو آگے لانے کے لیے ہیں جوان کی شخصیت اور خیالات میں تبدیلی لانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ‘‘۔ (۹)
لیکن اِسی ملک کے بعض قدامت پسند آج بھی تانیثیت کو ایک ’’غیر اسلامی تصور‘‘ قرار دیتے ہیں، اور اس پر گفتگو کرنے سے احتراز کرتے ہیں۔ اگر معروف اسلامی اسکالر اصغر علی انجینئر سے، جو ان دنوں ممبئی کے ایک اسلامی تحقیقی ادارے ’انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز‘ کے سربراہ ہیں، یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا واقعی اسلامی نقطۂ نظر سے اس اصطلاح (تانیثیت) کا استعمال قابلِ اعتراض ہے؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ ’ایسا قطعی نہیں ہے‘۔ اصغر علی انجینئر اپنے ایک مضمون ’’اسلامی تانیثیت‘‘ میں اس خیال کی وضاحت یوں کرتے ہیں :
’’واقعہ یہ ہے کہ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے باقاعدہ طور پر عورت کو اس وقت اختیارات دیے جب وہ مکمل طور پر مرد کی تابع دار سمجھی جاتی تھی یعنی اس زمانے میں جب عورت کے خود مختار ہونے اور پر وقار طریقے سے مساوات کی حق دار ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ (۱۰)
تانیثیت کی تعریف بیان کرتے ہوئے وہ اپنے متذکرہ مضمون میں لکھتے ہیں :
’’دیکھنا یہ ہے کہ تانیثیت یا Feminismسے ہم کیا مراد لیتے ہیں۔ اور اس کا جواب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ یہ عورت کو طاقت ور بنانے کی ایک تحریک ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے بارے میں یہ سوچنے کی کہ اسے بھی مکمل انسان کا درجہ دیا جائے، نہ کہ اسے بقول Simone de Beauvoire ایک دوسری جنس (Second Sex)سمجھ لیا جائے‘‘۔ (۱۱)
اصغر علی انجینئر کا یہ خیال ہے کہ قرآن نے عورت کو جو اختیار اور مرد کے مساوی جو درجہ دیا تھا، اس پر اسلامی معاشرے میں عمل درآمد نہیں ہوا اور وہاں مردانہ برتری ہی کی صورت قائم رہی۔ ان کے قول کے مطابق ان معاشروں میں ’’قرآنی فرامین کو یا تو نظر انداز کر دیا گیا یا ان کی وہ تعبیرات پیش کی گئیں جو مردانہ اقتدار کے موافق تھیں ‘‘۔ چنانچہ انجینئر صاحب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ’’اب وقت آگیا ہے کہ قرآن کی اصل روح کو سمجھا جائے‘‘۔ (۱۲) انھوں نے ایک ایسی ’’مہم‘‘ چھیڑنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے جس کے ذریعے مسلم خواتین اپنے ’’قرآنی حقوق‘‘ سے آگاہ ہوسکیں۔ اسلامی تانیثیت سے ان کی مراد گویا یہی ہے۔
اصغر علی انجینئر نے اسلامی تانیثیت اور مغربی تانیثیت کے فرق کو بھی واضح کر دیا ہے۔ سب سے پہلے انھوں نے یہ بات کہی ہے کہ ’’اسلامی تانیثیت کی بنیاد ان اقدار پراستوار ہے جن کے بارے میں کسی بھی سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ‘‘۔ (۱۳) مسلم خواتین کی آزادی کے بارے میں انھوں نے یہ بات کہی ہے کہ ’’ آزادی کی کچھ اسلامی ذمہ داری بھی ہے‘‘۔ واضح رہے کہ مغرب میں آزادیِ نسواں کے دوسرے معنی لیے جاتے ہیں۔ وہاں آزادی سے مراد جنسی آزادی یا جنسی بے راہ روی بھی ہے جس کے ’’مبتذل‘‘ شکل اختیار کر لینے کے امکانات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علی الرغم اسلام میں جنسی رویے کے سلسلے میں سخت قوانین وضع کیے گئے ہیں جن کی رو سے مرد اور عورت دونوں کو جنسی لطف اندوزی کا حق حاصل ہے، لیکن صرف ازدواج کے دائرے میں رہ کر۔ چنانچہ جیسا کہ اصغر علی انجینئر نے بھی کہا ہے کہ ’’ازدواج کی حدود سے باہر کسی بھی طرح کی جنسی آزادی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے‘‘۔ (۱۴)
اصغر علی انجینئرنے مغربی تانیثیت کے اُس رخ کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے جہاں عورت کی جنسیت کا استحصال تجارتی اور کاروباری مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے ’’یہ عورت کی عزت اور وقار کی توہین ہے۔ ۔ ۔ یہ اسلامی تانیثیت کے سراسر منافی ہے۔ ‘‘(۱۵)
اس بحث و تمحیص سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ’’اسلامی تانیثیت‘‘ کوئی قابلِ اعتراض یا ممنوع شے نہیں ہے، بلکہ یہ مسلم خواتین کے حقوق کی پاس داری ہے تاکہ وہ مردوں کے شانہ بہ شانہ معاشرے میں عزت و وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، لیکن اسلامی فریم ورک میں رہ کر۔ (۱۶)
واضح رہے کہ کوئی بھی اسلامی تانیثیت پسند(Islamic Feminist)قرآن و حدیث اور شریعت کے احکامات سے صرفِ نظر کر کے حقوقِ نسواں یا آزادیِ نسواں کی پاس داری و حمایت کا اعلان نہیں کر سکتا /کر سکتی، اور نہ ہی کوئی اسلامی تانیثی تھیوری اسلامی نظری ڈسکورس کو بنیاد بنائے بغیر تشکیل دی جا سکتی ہے۔
یہاں اس امر کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ہر چند کہ اسلامی تانیثیت اور مغربی تانیثیت میں تفاوت موجود ہے، تاہم مغربی تانیثیت کے بعض اثرات عہدِ حاضر کی اسلامی دنیا میں صاف نظر آتے ہیں۔ یہ مغرب کی ’لبرل تانیثیت‘ ہی کا اثر ہے کہ کئی مسلم خواتین مسلم اکثریتی ممالک کی سربراہ بنیں، مثلاً انڈونیشیا میں میگاوتی سوکارنوپتری صدر کے عہدے پر، پاکستان میں بے نظیر بھٹو وزیرِ اعظم کے عہدے پر، بنگلہ دیش میں خالدہ ضیا اور شیخ حسینہ واجد وزیرِ اعظم کے عہدوں پر، ٹرکی میں تانسو چیلر (Tansu Ciller)صدر کے عہدے پر، اور کرغستان میں روزہ عوتن بیے وا (Roza Otunbayeva) صدر کے عہدے پر فائز ہوئیں۔ شیخ حسینہ واجد آج بھی بنگلہ دیش کی وزارتِ عظمیٰ کا عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں۔
———-
تانیثیت کے ڈسکورس کا نئی ادبی تھیوری سے گہرا تعلق ہے۔ تانیثیت نے تنقیدی تھیوری کو بھی گہرے طور پر متاثر کیا ہے، بلکہ اس نے اپنی ایک علاحدہ تھیوری، ’’تانیثی تنقیدی تھیوری‘‘ بھی تشکیل دے دی ہے۔ ’گائینوکریٹی سزم‘ (Gynocriticism) جسے ہم ’نسائی تنقید‘ کہہ سکتے ہیں، تانیثی تنقید ہی کا ایک حصہ ہے۔ اردو کے تناظر میں تانیثی تنقید کے عملی و اطلاقی پہلو اور نمونے بھی سامنے آنے لگے ہیں، لیکن یہ مباحث خاصی توجہ کے متقاضی ہیں جن کی اس مختصر سے مقالے میں گنجائش نہیں نکل سکتی۔
حواشی
۱- بعض طبی ماہرین کا خیال ہے کہ عورتیں اپنی ہارمون کیمسٹری کی وجہ سے زیادہ جذباتی ہوتی ہیں۔
۲- ابھینو گپت نے ’شرنگاررس‘ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وہ ’’جذبہ‘‘ ہے جو ’’فرد کی جنس کو بیدار کرتا ہے ‘‘۔ (بہ حوالہ قاضی عبدالستار، ’جمالیات اور ہندوستانی جمالیات‘، [علی گڑھ: ادبی پبلی کیشنز، آنند بھون، ۱۹۷۷ء]، ص۴۰۔ )
۳- کسی منچلے شاعر نے فارسی کی مشہور ضرب المثل ’’داشتہ آید بہ کار‘‘ کو مزاحیہ انداز میں مصرعے کی شکل دے کر اس میں ذو معنیت پیدا کر دی ہے۔
۴- میری وول اسٹون کریفٹ (۱۷۵۹ تا۱۷۹۷ء) اٹھارویں صدی کی، برطانیہ کی معروف دانشور، فلسفی اور ناول نگار گذری ہے جس نے حقوقِ نسواں کی حمایت و پاس داری کے لیے زبردست جدو جہد کی۔ افسوس کہ صرف ۳۸سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔
۵- ان مباحث کے لیے دیکھیے ڈرو سیلا کارنیل (Drucilla Cornell)کی کتاب
At the Heart of Freedom: Feminism, Sex and Equality. (پرنسٹن، نیوجرسی: پرنسٹن یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۸ء)۔
۶- مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے این سی۔ ہرمن اور ایبی گیل جے۔ اسٹیوارٹ (Ann C.Hermann and Abigail J. Stewart)کی مرتبہ کتاب Theorizing Feminism (بولڈر :ویسٹ وئیوپریس، ۲۰۰۱ء)۔
۷- دیکھیے لارا برونیل (Laura Brunell)کا مضمون "Feminism Re-imagined :The Third Wave”مشمولہ Encyclopedia Britannica Book of the Year (شکاگو : انسائی کلوپیڈیا برٹینیکا Inc.، ۲۰۰۸ء)۔
۸- روز میری ٹونگ (Rosemarie Tong)، Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction، تیسرا ایڈیشن (بولڈر:ویسٹ وئیوپریس، ۲۰۰۹ء)، ص۲۸۴۔
۹- عذرا بانو، ’’صنفِ نازک تو بالاتر ہے‘‘، مطبوعہ روزنامہ ’انقلاب‘، ممبئی (علی گڑھ)، جلد ۷۴، شمارہ نمبر ۳۲۳(مورخہ ۲۶؍ نومبر۲۰۱۱ء)، ص۶۔
۱۰- دیکھیے اصغر علی انجینئر کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ شدہ مضمون ’’اسلامی تانیثیت‘‘(ترجمہ : اطہر پرویز)، مطبوعہ سہ ماہی ’اردو ادب‘ (نئی دہلی)، کتاب ۳۵۲ (اپریل، مئی، جون۲۰۱۱ء)، ص ۹۸۔
۱۱- ایضاً۔
۱۲- ایضاً، ص۹۹۔
۱۳- ایضاً۔
۱۴- ایضاً، ص ۱۰۰۔
۱۵- ایضاً، ص۱۰۱۔
۱۶- مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے اصغر علی انجینئر کی کتاب Rights of Women in Islam (اسٹرلنگ پبلشر ز، ۱۹۹۲ء)۔
٭٭٭
معاصر تنقیدی رویّے اور ناصر عباس نیّر
اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ادبی تنقید اب بین العلومی (Interdisciplinary) بن چکی ہے، اور معاصر سماجی علوم سے اس کا رشتہ کافی حد تک استوار ہو چکا ہے۔ تنقید کا اب وہ مفہوم، مقصد اور فنکشن نہیں رہا جوپہلے متصور کیا جاتا تھا۔ تنقیدی رویوں میں اس انقلابی نہج کی تبدیلی کا آغاز گذشتہ صدی کی دوسری دہائی سے ہوتا ہے جب سوویت یونین میں ہیئت پسندی(Formalism)، اور فرانس میں لسانیاتِ جدید (Modern Linguistics) کی داغ بیل پڑتی ہے۔ فرڈی نینڈ ڈی سسیور (م۱۹۱۳ء) لسانیاتِ جدید کا ابو الآبا تسلیم کیا گیا ہے جس کے فلسفۂ لسان نے معاصر تنقیدی رویوّں کو گہرے طور پر متاثر کیا ہے۔
ناصر عباس نیرّ کا شمار عہدِ حاضر کے اردو کے ان کشادہ ذہن ناقدین میں ہوتا ہے جو نہ صرف نئی ادبی تھیوری کی آگہی رکھتے ہیں، بلکہ جنھیں نئے تنقیدی رویوّں کے لسانیاتی مضمرات کا بھی احساس ہے۔ اس احساس و آگہی کے بغیر نہ تو ساختیات و پس ساختیات سے انصاف کیا جا سکتا ہے اور نہ نشانیات و اسلوبیات سے، اور نہ ہی کسی اور معاصر تنقیدی رویّے سے۔
گذشتہ صدی کے آخری چند دہوں کے دوران مختلف سائنسی وسماجی علوم میں جو غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے، اس کے اثرات عالمی سطح پر تنقیدی رویوّں پر بھی چیلنج کی صورت میں مرتسم ہوئے ہیں۔ ناصر عباس نیرّ اردو کے تناظر میں ہر نئے چیلنج سے نبرد آزما ہونے کی بھر پور علمی و فکری صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی حالیہ تصنیف ’لسانیات اور تنقید‘ (اسلام آباد: پورب اکادمی، ۲۰۰۹ء) ان کی اس صلاحیت کا بینّ ثبوت ہے۔ اس کتاب میں ۱۴ مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ بہ قولِ مصنف’’ یہ مختلف موضوعات پر نظری اور عملی تنقیدی مضامین ہیں، مگر ان میں باطنی سطح پر ایک ہم آہنگی نظر آئے گی، ایک خاص تنقیدی موقف دکھائی دے گا، ادب، تاریخ، زبان، نظریات کو جانچنے کی ایک ’پوزیشن‘ محسوس ہو گی‘‘ (ص۸)۔ اس کتاب کے مضامین کے بارے میں ستیہ پال آنند (جنھوں نے اس کتاب کا دیباچہ تحریر کیا ہے)، لکھتے ہیں کہ ’’ میں نے ان مضامین کو اپنی علالت کے باوجود بے حد خوشی سے پڑھا۔ کچھ نکتے تو ایسے تھے جن کے بارے میں میری واقفیت محدود تھی اور ان مضامین نے اس میں اضافہ کیا۔ ان کیRange and reach اتنی وسیع ہے کہ انھیں پڑھنے اور سمجھنے کے لیےEncyclopedic knowledge کی ضرورت ہے‘‘ (ص ۲۲)۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ ناصر عباس نیرّ کا نئی تنقیدی تھیوری اور اس کے مضمرات کا مطالعہ نہایت وسیع ہے۔ وہ نئے ذہنی و فکری رویوّں کے زیرِ اثر فروغ پانے والے تنقیدی رجحانات و میلانات کے نظری پہلوؤں سے کماحقہ، واقفیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے عملی و اطلاقی نمونے پیش کرنے کی بھی غیر معمولی اہلیت واستعداد رکھتے ہیں۔ ان کا ذہنی افق ساختیاتی، پس ساختیاتی اور رد تشکیلی نظریات سے لے کر مابعد جدیدیت، مظہریت، نوتاریخیت اور تانیثیت، نیز گلوبلا ئزیشن اور مابعد نوآبادیاتی صورتِ حال تک پھیلے ہوئے تمام تصورات اور فکری جہات کا بہ خوبی احاطہ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں انھیں ادبی تاریخ، ادبی تحریک، اور تحقیق و تنقید کے نئے پیرا ڈایم کا بھی فہم و ادراک ہے، اور ادب، لسانیات اور تنقید کے باہمی رشتوں پر بھی ان کی نظر بہت گہری ہے۔
متذکرہ کتاب کے ایک سیر حاصل مضمون ’’ساختیات۔ ۔ ۔ حدود اور امتیازات‘‘ میں ناصر عباس نیرّ نے ساختیات کی بنیادی فکر سے بحث کرتے ہوئے ان اعتراضات کا کافی و شافی جواب دیا ہے جو ساختیات پر اکثر کیے جاتے رہے ہیں۔ انھوں نے اس مضمون میں ہمارے یہاں ساختیات کے دیر سے فروغ پانے کی ثقافتی، فکری اور علمی وجوہ بھی بیان کی ہیں۔ ان کے خیال میں ہمارے یہاں ساختیاتی مباحث اسیّ کی دہائی میں اس وقت شروع ہوئے جب مغرب میں پس ساختیاتی مباحث کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر چند کہ پس ساختیاتی فکر، ساختیات کے بعد معرضِ وجود میں آئی، تاہم ساختیات کے مباحث ختم نہیں ہوئے۔ ساختیاتی فکر آج بھی پس ساختیات اور مابعد جدیدیت کے مباحث میں پس منظر کے طور پر جاری وساری ہے۔ ناصر عباس نیرّ کا یہ خیال بالکل درست ہے کہ ’’ جملہ پس ساختیاتی نظریات (جیسے ڈی کنسٹر کشن، نوتاریخیت، نومارکسیت، نو تحلیلِ تفسی، تانیثی تنقید، وغیرہ ہم) پر مدلل گفتگو ساختیات کی کامل تفہیم کے بغیر ممکن نہیں ‘‘ ( ص۶۶)۔ ناصر عباس نے بجا طور پر سِوس ماہرِ لسانیات فرڈی نینڈ ڈی سسیور کو’’ساختیات کا بانی‘‘ قرار دیا ہے۔
اپنے ایک اور مفصل مضمون ’’مابعد جدیدیت کا فکری ارتقا‘‘ میں ناصر عباس نیرّ نے مابعد جدیدیت کے نئے چیلنج سے مدلل انداز میں بحث کی ہے۔ ان کے خیال میں مابعد جدیدیت کاڈسکورس۱۹۶۰ء کی دہائی میں قائم ہوا۔ ۱۹۷۰ء کی دہائی میں اس کا ’’چرچا‘‘ جامعات کی سطح پر ہونے لگا اور زیادہ تر ’’ثقافتی مطالعات‘‘ تک محدود رہا، لیکن ۱۹۸۰ء کی دہائی میں مابعد جدیدیت آرٹ، ادب، فلسفے اور دیگر شعبوں میں زیرِ بحث آنے لگی۔ یہ بات نہایت دل چسپ ہے( جس کی طرف اشارہ ناصر عباس نیرّ نے بھی کیا ہے) کہ مابعد جدیدیت کا ڈسکورس اولاً آرکی ٹیکچر میں رائج ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرے شعبوں میں اس کی پذیرائی ہوئی۔ ناصر عباس نے نہایت پتے کی بات کہی ہے کہ مابعد جدیدیت اور پس ساختیات کے مباحث میں ’’ معاصریت‘‘ یعنی ہم زمانی کا رشتہ ہے، کیوں کہ ان کے بہ قول ’’جب آرکی ٹیکچر میں مابعد جدیدیت موضوعِ بحث بن رہی تھی، تب یورپ کی دانشورانہ فضا پر ساختیات کا غلبہ تھا، اور جب مابعد جدیدیت جامعات میں پہنچ رہی تھی اس وقت پس ساختیات کے مباحث عام ہو رہے تھے( اور پس ساختیات میں دریدا کی ڈی کنسٹرکشن اور میشل فوکو[کے] نظریات بہ طورِ خاص اہم ہیں )‘‘(ص۹۵)۔ اپنے ایک اور مضمون ’’مابعد جدید عہد میں ادب کا کردار‘‘ میں ناصر عباس نیرّ نے مابعد جدیدیت کے فکری مباحث کا رخ ادب کی جانب موڑتے ہوئے یہ سوال اٹھایا ہے کہ مابعد جدید عہد میں ادب کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ان کا یہ سوال تمام مابعد جدید ناقدین کو دعوتِ فکر دیتا ہے۔
ناصر عباس نیرّ نے اس کتاب میں جدیدیت کی فکری اساس کو بھی اپنی بحث کا موضوع بنایا ہے (دیکھیے مضمون’’ جدیدیت کی فکری اساس‘‘)۔ جدیدیت کے موضوع پر اردو میں اب تک جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہیں۔ ان کے خیال میں جدیدیت پر اردو میں لکھے گئے مقالات ایک ’’عجیب انتشار‘‘ کو پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ’’جدیدیت کے مرکزی تعقلات کی وضاحت میں خوب آزادی سے کام لیا گیا اور ان تعقلات کی تعبیر میں من مانی کی گئی ہے‘‘( ص۱۵۶)۔ ناصر عباس نے آل احمد سرورؔ، ن۔ م۔ راشد، وزیر آغا، شمیم حنفی اور محمد حسن کی تنقیدی تحریروں سے اقتباسات پیش کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ ’’اردو میں جدیدیت کوAll-inclusive اصطلاح کے طور پر برتا گیا ہے۔ اس ایک اصطلاح سے وہ سارے مطالب وابستہ کر دیے گئے ہیں جو جدیدیت کے ممکنہ اور لغوی معنی ہیں ؛ جو بیک وقت ماڈرینٹی اور ماڈرن ازم کے ہیں اور وہ معانی بھی جو نہ ماڈرنیٹی کے ہیں نہ ماڈرن ازم کے، محض ایجادِ بندہ ہیں ‘‘ (ص ص ۵۷-۱۵۶)۔ ناصرعباس نے بڑی وضاحت اور دلائل کے ساتھ انگریزی اصطلاحات ’’ماڈرنیٹی‘‘ او ر ’’ماڈرن ازم‘‘ کے درمیان فرق کو بتلایا ہے۔ ہمارے اکثر ناقدین انگریزی کی مذکورہ دونوں اصطلاحوں کے لیے لفظ ’’جدیدیت‘‘ ہی استعمال کرتے رہے ہیں، ناصر عباس نے ماڈرینٹی کے لیے ’’جدیدیت اول‘‘ اور ماڈرن ازم کے لیے ’’جدیدیت دوم‘‘ کی اصطلاحیں استعمال کی ہیں تاکہ خلطِ مبحث نہ ہونے پائے۔
ناصرعباس نیرّ نے اپنی متذکرہ کتاب کے ایک مضمون ’’اقبال اور جدیدیت‘‘ میں یہ خیال پیش کیا ہے کہ ہر چند کہ اقبال مغربی ادبیات سے پورے طور پر واقف تھے، تاہم ماڈرن ازم، جو اقبال کی معاصر یورپی تحریک تھی، کے براہِ راست اثرات ان کی شاعری پر نظر نہیں آتے۔ اس سلسلے میں ناصر نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا اقبال اس تحریک سے آگاہ نہیں تھے، اور اگر آگاہ تھے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی نظرِ انتخاب اس تحریک کو ان کے شعری مقاصد سے ہم آہنگ نہ محسوس کرتی ہو۔ کافی بحث و تمحیص کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اقبال پر مغربی جدیدیت کے اثرات نہیں تھے۔ ان کے خیال کے مطابق اقبال نے مغربی ادبیات سے اخذواستفادے کا عمل اپنے ابتدائی دور میں شروع کیا تھا اور ۱۹۱۰ء تک ان کا شعری مائنڈسیٹ متشکل ہو چکا تھا۔ واضح رہے کہ مغرب میں ماڈرن ازم کی تحریک کا زمانہ ۱۹۱۰ تا۱۹۳۰ء قرار دیا گیا ہے۔ ناصر عباس لکھتے ہیں کہ ’’جن دنوں [مغرب میں ] ماڈرن ازم کی تحریک زور شور سے جاری تھی، اقبال مغربی تہذیب پر تنقید کا آغاز کر چکے تھے، اور ماڈرن ازم مغربی تہذیب ہی کا جمالیاتی مظہر ہے‘‘( ص۱۲۷)۔ اقبال کے ماڈرن ازم سے راست ربط و ضبط نہ رکھنے کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اقبال ’’ ایک مختلف تصورِ کائنات اور مائنڈ سیٹ کے علم بردار تھے‘‘، اسی لیے انھوں نے ماڈرن ازم سے کوئی سروکار نہیں رکھا۔
اپنی کتاب’لسانیات اور تنقید‘ میں ناصر عباس نیرّ نے فکشن کی تنقید، ادبی تاریخ نویسی میں تنقید کی اہمیت، اور ادب اور ادبی تحریک جیسے مباحث سے بھی اپنی دل چسپی کا اظہار کیا ہے۔ فکشن کی تنقید کے سلسلے میں انھوں نے پرانے اور نئے دونوں نظری مباحث اٹھائے ہیں۔ پرانے نظریے(روسی ہیئت پسندی اور ساختیات کے ارتقا سے قبل کا نظریہ) کی رو سے فکشن کا زندگی سے گہرا اور اٹوٹ رشتہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن نئے نظریے نے، جوروسی ہیئت پسندوں کا نظریہ تھا، ’’فکشن کو زندگی اور خارجی حقیقت سے الگ کر کے دیکھا اور اس امر کو باور کرانے کی سعی کی کہ فکشن کی ایک اپنی حقیقت ہے اور وہ کسی دوسری اور خارجی حقیقت پر منحصر نہیں ‘‘(ص ۲۲۵)۔ ادبی تاریخ نویسی کے سلسلے میں ناصر نے تنقید کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ ’’تنقید کو تاریخ سے جدا نہیں کیا جا سکتا‘‘۔ انھوں نے اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ادبی تاریخ نویسی میں تحقیق کو تنقید پر فوقیت دیتے ہیں، مثلاً گیان چند جین اور رشید حسن خاں کا موقف ہے کہ تحقیق سے صرفِ نظر کر کے ادبی تاریخ نہیں لکھی جا سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اصلاً ’’محقق‘‘ ہیں۔
ناصر عباس نیرّ کی علمی دل چسپی کا موضوع ’’نوآبادیاتی صورتِ حال‘‘ بھی ہے۔ چنانچہ اس عنوان سے لکھے ہوئے اپنے ایک مضمون میں انھوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جہاں ایسی صورتِ حال پیدا ہو جاتی ہے وہاں ’’دو دنیاؤں ‘‘ کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔ ایک دنیا وہ ہوتی ہے جو نو آبادکار کی دنیا کہلاتی ہے، اور دوسری دنیا نو آبادیاتی یا مقامی باشندوں کی دنیا ہوتی ہے۔ یہ دونوں دنیائیں ایک دوسرے کی ’’ضد‘‘ ہوتی ہیں۔ البرٹ میمی (Albert Memmi) کے خیال سے اتفاق کرتے ہوئے ناصر عباس کہتے ہیں کہ نوآبادیاتی باشندوں کے لیے دوہی صورتیں ہوتی ہیں، ’’ انجذاب‘‘ یا ’’بغاوت‘‘۔ انجذاب کی صورت میں ’’ نوآبادیاتی باشندہ یا تونو آباد کار جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی شخصیت، ثقافت، نظامِ فکر، اقداری نظام کو مکمل طور پر جذب کرنے کی سعی کرتا ہے، یا پھر اس کے خلاف بغاوت کرتا اور اپنی باز یافت کے عمل سے گذرتا ہے‘‘(ص۲۸)۔
آج کی دنیا گلوبلا ئزیشن یا عالم کاریت کی زد میں آ کر ایک گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے جس سے چھوٹی اور اقلیتی زبانوں کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ناصر عباس نیرّ نے اپنے مضمون ’’گلوبلایزیشن اور اردو زبان‘‘ میں اسی موضوع پر اظہارِ خیال کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ ’’گلوبلایزیشن ثقافتی ولسانی یکسانیت کی زبردست مداح اور مابعد جدیدیت کے برعکس ثقافتی ولسانی تنوع(Diversity) کی مخالف ہے‘‘(ص ۱۹۱)۔ گلوبلایزیشن نے اردو زبان کو کئی زاویوں سے متاثر کیا ہے جن کا ذکر ان کے اس مضمون میں ملتا ہے۔
متذکرہ کتاب کے آخری دو مضامین جن میں افسانوی تنقید اور تحقیق کے پیرا ڈایم کی بات کہی گئی ہے انتہائی فکر انگیز ہیں اور نہایت توجہ سے پڑھے جانے کے متقاضی ہیں۔ یہ مضامین جامعاتی سطح پر کام کرنے والے تحقیق کاروں کے لیے نئی روشنی فراہم کرتے ہیں اور تحقیقی طریقِ کار کے نئے در وا کرتے ہیں۔
مذکورہ کتاب کا ایک اور مضمون بھی لائقِ توجہ ہے جس میں ناصر عباس نیرّ نے فراقؔ گورکھپوری کے لفظی پیکروں (تمثالوں ) کو اپنے مطالعے اور تجزیے کا موضوع بنایا ہے۔ فراقؔ کی شاعری کی خاطر خواہ تحسین اس وقت تک ممکن نہیں ہوسکتی جب تک کہ ہم ان کے شعری پیکروں کوAppreciate نہ کریں۔ ہمارے ناقدین فراق کی شاعری پر گفتگو کرتے وقت اکثر اس پہلو سے صرفِ نظر کر جاتے ہیں، لیکن ناصر عباس نے بڑی دقتِ نظر اور انتہائی معروضیت کے ساتھ ان پیکروں (Images) کا مطالعہ اپنے مضمون ’’کلامِ فراق کے لفظی پیکر‘‘ میں پیش کیا ہے۔ اس مطالعے سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ فراق کے لفظی پیکروں میں ’’ ہندوستانیت کی بوباس‘‘ رچی بسی ہے، اس میں ’’ ایمائیت، تمثیلیت اور استعاراتی پہلو‘‘ پائے جاتے ہیں، نیز یہ شاعر کے ’’جمالیاتی تجربے‘‘ کی عکاسی کرتے ہیں اور شاعرانہ تخلیقی عمل سے ایک ’’نامیاتی ربط‘‘ رکھتے ہیں۔
ناصر عباس نیر کی زیرِ مطالعہ کتاب ’لسانیات اور تنقید‘ نئے تنقیدی رویوں اور معاصر تنقیدی میلانات و رجحانات پر ایک نہایت قابلِ قدر علمی دستاویز ہے۔ اس کے تمام مقالات ایک عالمانہ شان اور دانشورانہ آن بان رکھتے ہیں، اور مصنف کے گہرے اور وسیع مطالعے کے غماز ہیں۔ ناصر کا طرزِ استدلال سائنسی و معروضی ہے۔ وہ کسی موضوع پر قلم اٹھاتے وقت تحقیق اور چھان بین سے بھی کام لیتے ہیں۔ نئی ادبی تھیوری اور اس کے مضمرات پر ان کی نظر بہت گہری اور گرفت کافی مضبوط ہے۔ انھوں نے نئی تھیوری کے تمام معاملات پر انتہائی سنجیدہ غور و فکر سے کام لیا ہے۔
یہ کتاب نئی ادبی تھیوری، نئے ڈسکورس، نئے مباحث اور نئے تنقیدی رویوّں کی افہام و تفہیم کی ایک کامیاب کوشش سے تعبیر کی جا سکتی ہے۔
٭٭٭
مابعد جدیدیت کا نیا چیلنج اور وہاب اشرفی
پروفیسر وہاب اشرفی کا شمار اردو کے ان مقتدر ناقدین میں ہوتا ہے جنھوں نے نئی ادبی تھیوری کے معاملات کی چھان بین نہایت لگن، انہماک اور دقتِ نظر کے ساتھ کی ہے، اور اس کی روشنی کو نئی نسل تک پہنچانے کا فریضہ بھی انجام دیا ہے۔ ’مابعد جدیدیت: مضمرات و ممکنات‘(الہ ٰ آباد: کتاب محل، ۲۰۰۲ء)، نہ صرف ما بعد جدیدیت کے حوالے سے نئی تھیوری پران کی ایک مایۂ ناز تصنیف ہے، بلکہ اس موضوع پر آئندہ کام کرنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بھی ہے۔ مغرب میں مابعد جدیدیت سب سے پہلے آر کی ٹیکچر(عمارت سازی ) میں ایک رجحان کی نمائندگی کے طور پر رائج ہوئی۔ اس کے بعد یہ ادب، آرٹ، اور فلسفے میں بحث کا موضوع بنی۔ اردو کی دانشورانہ فضا میں اس کی گونج بہت بعد میں سنائی دی۔ جس زمانے میں (۱۹۶۰ء کے لگ بھگ) مابعد جدیدیت آر کی ٹیکچر میں فروغ پا رہی تھی، ٹھیک اسی زمانے میں مغرب میں ساختیات کے مباحث بھی جاری تھے۔ بعد میں ساختیات سے پس ساختیاتی فکر کی تشکیل عمل میں آئی اور جامعاتی سطح پر مابعد جدیدیت ایک نئے تنقیدی رویّے کے طور پر رائج ہونے لگی۔
وہاب اشرفی نے ذہنی سطح پرا ن تینوں مکاتبِ فکر کے اثرات قبول کیے ہیں، لیکن مابعد جدیدیت اور اس کے مضمرات و ممکنات پران کی نظر بہت گہری ہے۔ انھوں نے مابعد جدیدیت کو بہ طورِ خاص اپنی فکری جولاں گاہ بنایا ہے جس کا روشن ثبوت ان کی متذکرہ کتاب ہے۔ جس طرح ساختیات کوسمجھے بغیر پس ساختیات کا سمجھنا مشکل ہے، اسی طرح مابعد جدیدیت کی افہام و تفہیم بھی ساختیاتی فکر سے واقفیت کی متقاضی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاب اشرفی مابعد جدیدیت کے فکری پس منظر کے طور پر ساختیاتی، پس ساختیاتی اور رد تشکیلی فکر، اور نئی روشنی کے دیگر تصورات کو اکثر زیرِ بحث لاتے ہیں۔ اس طرح وہ نئی تھیوری اور نئے ڈسکورس کے حوالے سے پورے عالمی منظر نامے کی خبر رکھتے ہیں۔
’مابعد جدیدیت: مضمرات و ممکنات‘ گیارہ ابواب پر مشتمل ہے جنھیں دو زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے زمرے میں چھے ابواب شامل ہیں جن میں مابعد جدیدیت اور متعلقہ تصورات کے نظری پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ دوسرے زمرے میں پانچ ابواب ہیں جن میں اردو کے تناظر میں مابعد جدید فکر کو جانچا اور پرکھا گیا ہے۔ متذکرہ کتاب کے ان دونوں زمروں میں مابعد جدید نظریۂ تنقید کے علاوہ بعض دیگر معاصر تنقیدی نظریات و تصورات کی جھلک بھی صاف دکھائی دیتی ہے۔ انھوں نے کتاب کے پہلے ہی باب ’’مابعد جدیدیت کے تشکیلی پہلو‘‘ میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ مابعد جدیدیت کا تعلق کسی نہ کسی طرح ساختیات اور پس ساختیات سے رہا ہے۔ چنانچہ انھوں نے فرڈی نینڈڈی سسیور (۱۸۵۷ تا۱۹۱۳ء) کے لسانیاتی تصورات(فلسفۂ لسان) کو بنیاد بنا کر اس باب میں ان دونوں فکری جہات سے سیر حاصل بحث کی ہے۔
کتاب کا دوسرا باب ’’مابعد جدیدیت اور مغربی مفکرین‘‘ ہے جس میں وہاب اشرفی نے رولاں بارت، دریدا، مشل فوکو، لاکاں، لیوتار، لوئی آلتھو سے، اِہاب حسن، جولیاکر سٹیوا، ٹیری انگلیٹن، اور بعض دیگر مفکرین کے حوالوں سے نئی تھیوری کے مباحث کا بڑی فکری آگہی اور آگاہی کے ساتھ احاطہ کیا ہے۔ اس سے ان کے ذہنی ارتفاع کا پتا چلتا ہے۔ اس باب میں اہاب حسن کے حوالے سے انھوں نے مابعد جدیدیت اور جدیدیت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس میں ضمناً فضیل جعفری اور شمس الرحمن فاروقی کا بھی ذکر آگیا ہے۔ وہاب اشرفی نے ا س بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ فضیل جعفری نے یہ کیسے لکھ دیا کہ ’’وہاب اشرفی نے کبھی بھی مابعد جدیدیت کو ادب سے روشناس کرانے کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی اس کی تحریروں سے اس طرح کا کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے‘‘(ص۹۳)۔ فضیل جعفری کے اس بیان پر وہاب اشرفی اپنا ردِ عمل یہ لکھ کر ظاہر کرتے ہیں کہ ’’یہ کہنا کہ اہاب حسن نے کبھی بھی مابعد جدیدیت کو ادب سے روشناس کرانے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، ایک غلط دعویٰ ہے اور عدم آگہی پر دال ہے۔ میں اس بات کا احسا س دلانا چاہتا ہوں کہ اہاب حسن مابعد جدیدیت (اور جدیدیت) کے حوالے سے بہت کچھ لکھتا رہا ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ غیر ادبی پہلو کو بھی نشان زد کرتا ہے‘‘ (ص۹۹)۔ واضح رہے کہ اہاب حسن نے جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے تصورات پر اپنی کتاب(1987 )The Post-modern Turn ہی میں زیادہ تر لکھا ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ کتاب فضیل جعفری کی نظر سے نہ گذری ہو۔
کتاب کے تیسرے باب میں وہاب اشرفی نے ایڈورڈسعید، ہومی بھابھا اور گائتری کے حوالوں سے نوآبادیاتی اور مابعد نوآبادیاتی صورتِ حال کا مفصل جائزہ پیش کیا ہے۔ (وہاب اشرفی نے نہ جانے کیوں گائتری کے ساتھ’’چودھری‘‘ لگا دیا ہے اور ان کا نام ’’گائتری چودھری اسپاوک‘‘ لکھا ہے جب کہ ان کا نام گائتری چکرورتی اسپیوک [Gayatri Chakravorty Spivak] ہے اور عام طور پر وہ گائتری چکرورتی کے نام سے جانی جاتی ہیں )۔ ایڈورڈ سعید کی نوآبادیاتی فکر کا بنیادی ماخذ اس کی کتاب Orientalism ہے جس کا نچوڑ وہاب اشرفی نے یہ پیش کیا ہے کہ حکم راں بیرونی قوتیں اپنی رعایا کی خدمت کی آڑ میں اپنی طاقت کا فروغ چاہتی ہیں، چنانچہ جہاں جہاں بھی نوآبادیاتی سلسلے ہیں وہاں یہ صورت دیکھی جا سکتی ہے۔ وہاب اشرفی نے ایڈورڈ سعید کی فلسطینیوں کے کاز کی حمایت کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کے خیال میں ایڈورڈ سعید نے فلسطینیوں کے مسائل کو نہ صرف سمجھنے کی کوشش کی بلکہ اس کے صحیح رخ کو عوام اور دنیا کے سامنے رکھنے کا بھی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ ہومی بھابھا نے نوآبادیاتی و ما بعد نوآبادیاتی فکر کے سلسلے میں کوئی بہت خاص کام نہیں کیا، البتہ گائتری چکرورتی کو اس موضوع پران کے مقالے”Can the Subaltem Speak?” کی وجہ سے خاصی شہرت ملی۔ ژاک دریدا کی کتابOf Grammatology کے ترجمے اور اپنے انٹر وڈکشن کی وجہ سے بھی گائتری کافی مشہور ہوئیں۔ عملی مارکسسٹ ہونے کے علاوہ وہ رد تشکیلی مفکر اور تانیثیت پسند بھی ہیں۔ اس باب کے آخر میں وہاب اشرفی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نوآبادیات کی پوری بحث مابعد جدیدیت کے حوالے سے ہی ممکن ہے۔
متذکرہ کتاب کا چوتھا باب ’’مابعد جدیدیت: تاریخیت اور نئی تاریخیت‘‘ ہے۔ تاریخیت اور نوتاریخیت دونوں کا نئی ادبی تھیوری سے گہرا رشتہ ہے۔ وہاب اشرفی نے اس باب میں اس رشتے کو بہ خوبی اجاگر کیا ہے۔ اس ضمن میں باختن، آلتھو سے، ہیڈن وہائٹ اور فوکو کے حوالوں سے انھوں نے بڑی مدلل بحث کی ہے، اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ادب کا تاریخ سے اٹوٹ رشتہ ہے، اس لیے کہ تاریخ محض علم کا کوئی خزانہ نہیں ہے بلکہ اسے ادبی متن کے طور پربھی سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ادب اور تاریخ میں حدِ فاصل نہیں قائم کی جا سکتی۔
زیرِ مطالعہ کتاب کا پانچواں باب ’’مابعد جدیدیت اور تانیثیت‘‘ ہے۔ اس باب میں وہاب اشرفی نے مغرب میں تانیثی تحریک کے عہد بہ عہد ارتقا پر بڑی غائر نظر ڈالی ہے اور تانیثیت کی مختلف شکلوں، مثلاً ریڈیکل تانیثیت، لبرل تانیثیت، نفسیاتی تانیثیت، سماجی تانیثیت، وغیرہ کے اہم نکات پیش کیے ہیں۔ انھوں نے معروف تانیثی مفکر اینڈ ریز ہیسین(Andreas Huyssen) کے تانیثی تصورات سے بھی مفصل بحث کی ہے۔ اس باب میں وہاب اشرفی تانیثیت کے بارے میں اپنا موقف پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ’’بہر طور نسوا نیت کی تحریک کا کلیدی نکتہ یہ ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کم تر سطح کی مخلوق نہیں ہے۔ یوں تو یہ بات مغرب کے حوالے سے کہی جاتی ہے، لیکن مشرق میں بھی اس سے کچھ مختلف صورت نہیں ہے‘‘(ص ۱۴۸)۔
زیرِ نظر کتاب کا چھٹا باب دراصل زمرۂ اول کا تتمہ ہے جس میں شروع کے پانچ ابواب کے مباحث کے’’ نتائج‘‘ پیش کیے گئے ہیں۔ مصنف نے مابعد جدیدیت کے پچھلے مباحث کو اس باب میں اس خوبی کے ساتھ سمیٹا ہے کہ کہیں بھی تکرار کی صورت پیدا ہونے نہیں پائی ہے۔
کتاب کا زمرۂ دوم پانچ ابواب پر مشتمل ہے جس کے پہلے باب میں اردو مابعد جدیدیت کے اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ باب خاصا اہم ہے اور اہلِ اردو بالخصوص اردو ناقدین کو دعوتِ فکر دیتا ہے اور ذہن کے بہت سے جالے دور کرتا ہے۔ اس باب میں وہاب اشرفی نے اردو کے ’’معصوم‘‘ نقادوں اور ’’اردو ادب کی ترقی پسندی‘‘کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ مابعد جدیدیت کے بارے میں ان معصوم نقادوں کی پھیلائی ہوئی غلط اور بے بنیاد باتوں کا بھی انھوں نے کافی و شافی جواب دیا ہے۔ مابعد جدیدیت اور اس کے تصورات کے دفاع میں وہاب اشرفی کی یہ ایک نہایت سنجیدہ، سلجھی ہوئی اور صاف گوئی پر مبنی تحریر ہے جس کی داد نہ دینا علمی دیانت داری کے منافی ہے۔
زمرۂ دوم کے بعد کے تین ابواب میں ما بعد جدیدیت کے تناظر میں اردو شاعری، اردو فکشن، اور اردو تنقید کا عمیق جائزہ پیش کیا گیا ہے جس سے مابعد جدیدیت کے بہت سے اطلاقی و عملی پہلو اور نمونے بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اسی زمرے کے ایک باب میں انھوں نے پس ماندہ اور دلت طبقے کے استحصال اور دلت لٹریچر کے تاریخی پس منظر کا بھی جائزہ پیش کیا ہے۔ انھوں نے اس بات پراطمینان ظاہر کیا ہے کہ اردو کہانیوں اور ناولوں میں مابعد جدید رویّے کے تحت دلتوں اور پس ماندہ لوگوں کی زندگی کی عکاسی پر خاصا زور ملتا ہے۔
مابعد جدیدیت اور اردو شاعری کی بحث اٹھاتے ہوئے وہاب اشرفی نے واضح کر دیا ہے کہ ’’ہر زمانے کے ادب پر مابعد جدیدیت کے نقطۂ نظر سے بحث ہوسکتی ہے، بلکہ ہو گی ہی، ا س لیے کہ اس کے تمام نکات واضح طور پر کسی ایک عہد، زمانے یا رجحان میں قید نہیں، بلکہ یہ زمان و مکان کے بیحد وسیع تناظر میں اپنا کام سرانجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ‘‘(ص۱۷۸)۔ اس ضمن میں انھوں نے بہمنی دور کے ایک ممتاز شاعر فخر دین نظامی (نظامی بیدری) کی مثنوی ’’کدم راؤ پدم راؤ‘‘ کا ذکر کیا ہے کہ جس کا مطالعہ مابعد جدید نقطۂ نظر سے کیا جا سکتا ہے، کیوں کہ اس میں ہندو صنمیات کا ذکر کثرت سے ہوا ہے۔ اسی طرح عادل شاہی اور قطب شاہی دور کی قدیم (دکنی) شاعری بھی بہ قولِ وہاب اشرفی، ’’اپنی کلّی تفہیم کا جدید ترین رویّہ چاہتی ہے۔ ‘‘ وہ مصحفی، مرزا شوق، داغ اور بعض دیگر کلاسیکی شعرا کے اشعار نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان بزرگ شعرا کا مطالعہ مابعد جدید شعریات کے حوالے سے بہتر طور پر ممکن ہے۔ وہاب اشرفی نے آج کی اردو شاعری میں بھی مابعد جدید عناصر کی نشان دہی کی ہے اور مثال کے طور پر کچھ نظمیں پیش کی ہیں، مثلاً ’’شناختی کارڈ‘‘(حسن نواب)، ’’نارسائی‘‘( کفیل آذر)، ’’ ناموجود‘‘( احمد فراز)، ’’مکالمہ‘‘ (افتخار عارف)، ’’مدافعت‘‘ (ساقی فاروقی)، ’’دلوں کا فلسطین‘‘( اوصاف احمد)، ’’نئے تخلیق کار‘‘ (مخمور سعیدی)، ’’آٹھواں سمندر‘‘( خاطر غزنوی)، ’’اداسی کی ہجو‘‘( شہریار)’’ ایک دعا جو میں بھول گیا تھا‘‘ ( منیر نیازی)، ’’عہدِ وفا‘‘( اختر الایمان )، ’’ناریل کے پیڑ‘‘( بلراج کومل)، وغیرہ۔ اِن نظموں میں انھیں مابعد جدید رویوں اور مابعد جدید ذہنی میلانات کا پتا چلتا ہے۔ آج کل مابعد جدید غزلیں بھی خوب لکھی جا رہی ہیں، چنانچہ وہاب اشرفی نے غزل کے منظر نامے پر بھی مابعد جدید نقطۂ نظر سے نگاہ ڈالی ہے، اور شہریار، مظہر امام، حسن نعیم، سلطان اختر، حامدی کاشمیری، شجاع خاور، باقر مہدی، حنیف ترین، مظفر حنفی، شہزاد احمد، شمیم حنفی، صبا اکرام، ندا فاضلی، وغیرہ کی غزلوں کا تجزیہ مابعد جدید رویوں کی روشنی میں کیا ہے۔
وہاب اشرفی نے مابعد جدید رویوں کی نشان دہی اردو شاعری کے علاوہ اردو فکشن میں بھی کی ہے اور ایسے بے شمار ناولوں اور افسانوں کا ذکر کیا ہے جن میں مابعد جدید عناصر کی رمق پائی جاتی ہے۔ مابعد جدیدیت چوں کہ ثقافت پر زیادہ زور صرف کرتی ہے، اس لیے انھوں نے صرف ایسے افسانوں اور ناولوں کا تجزیہ پیش کیا ہے جو اپنی ثقافت کے زائیدہ ہیں یا اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ بعض ناولٹ اور ناول جن کا انھوں نے مابعد جدید نقطۂ نظر سے جائزہ پیش کیا ہے یہ ہیں : ’نمبر دار کا نیلا‘( سید محمد اشرف)، ’شب گزیدہ‘( قاضی عبدالستار)، ’نمک‘( اقبال مجید)، ’بستی‘( انتظار حسین)، ’ دوگز زمین‘ (عبدالصمد)، ’ فائر ایریا‘( الیاس احمد گدی)، ’مکان‘ (پیغام آفاقی)، ’ بولو مت چپ رہو‘ (حسین الحق)، ’ بادل‘ (شفق)، وغیرہ۔ ناولوں کے مابعد جدید تجزیوں کے ساتھ ساتھ وہاب اشرفی اردو افسانوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ’’اردو ناولوں کی طرح افسانے میں بھی کئی آوازیں ایسی ابھری ہیں جو مابعد جدیدیت کے نقطۂ نظر سے خاصی اہم جانی جاتی ہیں۔ ‘‘(ص ۳۳۸)۔ انھوں نے ایسے کئی اردوافسانوں کا ذکر کیا ہے جن میں مابعد جدیدیت کی کوئی نہ کوئی صورت نظر آتی ہے، حتیٰ کہ جدیدیت کے سرخیل شمس الرحمن فاروقی کے افسانے’’سوار‘‘ میں بھی انھوں نے مابعد جدید عنصر ڈھونڈ نکالا ہے۔ فاروقی کے بارے میں وہاب اشرفی کا یہ بیان خاصا چونکا دینے والا ہے:’’ ایسا لگتا ہے کہ شمس الرحمن فاروقی قطعاً اپنے وجود ی افکار سے الگ ہو گئے ہیں اور جدیدیت کی تمام تر شقوں کو فراموش کر دیا ہے۔ وہ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، ’سوار‘ مابعد جدیدیت کے زمرے ہی کی ایک مثالی کتاب ہے جس کی طرف بار بار جوع کرنا ناگزیر ہو گا‘‘( ص ۳۴۸)۔ شمس الرحمن فاروقی کے علاوہ، وہاب اشرفی کی اس تحریر میں، جن دوسرے افسانہ نگاروں کا ذکر مابعد جدید رویّے کے سلسلے میں آیا ہے ان میں شوکت حیات، شفیع مشہدی، مشتاق احمد نوری، محمود واجد، انیس رفیع، جابر حسین، مشرف عالم ذوقی، عابد سہیل، رضوان احمد، عبدالصمد، ساجد رشید، حسین الحق، شموئل احمد، پیغام آفاقی، سید محمد اشرف، طارق چھتاری کے نام خصوصیت کے ساتھ قابلِ ذکر ہیں۔ مابعد جدیدیت کے حوالے سے ان افسانہ نگاروں کا ذکر کرنے کے بعد وہاب اشرفی نے نیر مسعود کے افسانوی مجموعے ’طاؤسِ چمن کی مینا‘ کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ’سوار‘ کی طرح یہ افسانوی مجموعہ بھی ہماری زندگی کے وہ نقوش پیش کررہا ہے جو ہماری ’’ثقافتی میراث‘‘ رہے ہیں۔
وہاب اشرفی نے کتاب کے آخری باب’’ مابعد جدیدیت اور اردو تنقید‘‘ میں ان ناقدین کے نظری اور اطلاقی کاموں کا جائزہ لیا ہے جنھوں نے مابعد جدیدیت کے حوالے سے اردو تنقید کی کئی سمتوں اور جہتوں کو ’’روشن‘‘ کیا ہے۔ ان میں سب سے نمایاں نام پروفیسر گوپی چند نارنگ کا ہے۔
بلاشبہ گوپی چند نارنگ نے ساختیاتی اور پس ساختیاتی تصورات پر اردو میں بنیادی کا م کیا ہے جس کا اعتراف ہر اس شخص کو ہے جس نے نئی ادبی تھیوری کا بہ نظرِ غائر مطالعہ کیا ہے، لیکن ان کی فکری جولاں گاہ یہیں تک محدود نہیں۔ انھوں نے نئی تھیوری اور اس کے اطراف کو اپنی گراں قدر تحریروں سے پُر ثروت بنانے کے علاوہ مابعد جدید فکر سے بھی اپنی گہری آگہی کا ثبوت پیش کیا ہے، اور’ اردو مابعد جدیدیت پر مکالمہ‘ مرتب کرنے کے علاوہ مابعد جدید رویّے پر کئی اہم مضامین قلم بند کیے ہیں۔ وہاب اشرفی کا یہ قول صداقت پر مبنی ہے کہ ’’گو پی چند نارنگ نے نہایت عالمانہ طریقے پرنہ صرف مغربی مابعد جدیدیت، بلکہ اردو کی بھی مابعد جدیدیت کے سلسلے میں اتنا کچھ لکھ دیا ہے کہ اس کی تفہیم میں کوئی دشواری ہونی نہیں چاہیے‘‘( ص ۳۹۸)۔ مابعد جدید تنقید کے حوالے سے وہاب اشرفی نے گوپی چند نارنگ کے بعد وزیر آغا کا ذکر کیا ہے۔ جہاں تک راقم السطور کو علم ہے وزیر آغا کی ساختیاتی، پس ساختیاتی اور رد تشکیلی فکریات سے تو دل چسپی رہی ہے اور انھوں نے رولاں بارت اور دریدا کے حوالے سے بہت کچھ لکھا بھی ہے، لیکن مابعد جدید رویّے کے تعلق سے ان کی کوئی اہم اور قابلِ ذکر تحریر راقم السطور کی نظر سے نہیں گذری۔ بہر طور، وہاب اشرفی کے خیال میں وہ’’‘ داد‘‘ کے مستحق ہیں کہ بعض مغربی فکری نظام کو انھوں نے اپنے طور پر سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد نظام صدیقی کا نام آتا ہے جو ’’طویل مضامین ‘‘لکھنے کے ہنر سے بہ خوبی واقف ہیں۔ وہ ’’زود نویس‘‘ بھی ہیں، لیکن بہ قولِ وہاب اشرفی انھوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے بہت سوچ بچار کے بعد لکھا ہے، کیوں کہ ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ مابعد جدید تنقیدی رویّے کے ضمن میں وہاب اشرفی نے جن دوسرے ناقدین کی نگارشات کا جائزہ لیا ہے ان میں حامدی کاشمیری، ابوالکلام قاسمی، شافع قدوائی، دیویندر اسر، اور عتیق اللہ خاص ہیں۔
پاکستان میں وزیر آغا کے علاوہ قمر جمیل، فہیم اعظمی، اور ضمیر علی بدایونی بھی مابعد جدیدیت کے امکانات سے بحث کرتے رہے ہیں اور اس کے ڈسکورس کو آگے بڑھاتے رہے ہیں، چنانچہ وہاب اشرفی نے اپنے اِس تنقیدی جائزے میں ان تینوں ناقدین کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ناصر عباس نیر کو وہ نظر انداز کر گئے ہیں جو کافی عرصے سے نئی تھیوری پر مسلسل لکھ رہے ہیں اور مابعد جدید رویّے سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مضامین ’استعارہ‘ (نئی دہلی) میں بھی شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان کی کتاب ’جدیدیت سے پس جدیدیت تک‘ ۲۰۰۰ء میں شائع ہو چکی تھی۔
کتاب کے آخر میں شامل ’’آخری بات‘‘ کے عنوان سے اپنی دو صفحوں کی تحریر میں وہاب اشرفی نے کتاب کے جملہ مباحث کا مغز پیش کر دیا ہے اور اپنی بات اس جملے پر ختم کر دی ہے:’’قصہ مختصر کہ مابعد جدیدیت ہمیں اپنی جڑوں کی طرف لے جاتی ہے، ہماری ثقافت کی نیرنگی اور تنوع کے پس منظر میں نیا ادبی منظر نامہ پیش کرتی ہے جن سے کترانا اپنے سے روٹھنے کے مترادف ہے‘‘ (ص ۴۵۰)۔
مابعد جدیدیت بالخصوص اردو کے تناظر میں مابعد جدیدیت کے نئے چیلنج اور نئی ذہنی صورتِ حال کو سمجھنے کے لیے وہاب اشرفی کی اس کتاب کا مطالعہ ناگزیر ہے۔
٭٭٭
اسلوبیاتی نظریۂ تنقید اور مغنی تبسم
پروفیسر مغنی تبسم اردو کے ایک ممتاز شاعر ہونے کے علاوہ ایک معروف نقاد بھی تھے۔ انھیں تنقید نگاری کے میدان میں ایک نمایاں حیثیت اسی زمانے میں حاصل ہو گئی تھی جب آج سے تقریباً چالیس سال قبل فانی بدایونی پران کی تنقیدی کتاب منظرِ عام پر آئی تھی۔ یہ کتاب دراصل ان کا پی ایچ۔ ڈی۔ کا وہ تحقیقی مقالہ تھا جو انھوں نے عثمانیہ یونیورسٹی میں پروفیسر مسعودحسین خاں کی نگرانی میں تیار کیا تھا۔ اس مقالے کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اس کا معتدبہ حصہ کلامِ فانی کے صوتیاتی اور اسلوبیاتی تجزیوں پر مشتمل تھا۔ اردو میں پہلی بار اس جامعیت کے ساتھ کسی شاعر کے کلام کا صوتیاتی و اسلوبیاتی تجزیہ پیش کیا گیا تھا۔ مغنی تبسم کی اس کوشش کو غیر معمولی طور پر سراہا گیا۔ چنانچہ فانی پر اپنی کتاب کی اشاعت کے بعد سے انھوں نے بعض دیگر اردو شعرا کے کلام کا مطالعہ و تجزیہ بھی اسلوبیاتی نقطۂ نظر سے کرنا شروع کر دیا۔
یہاں اس امر کا ذکر بے جا نہ ہو گا کہ اسلوبیات درحقیقت لسانیاتی مطالعۂ اسلوب ہے۔ ادبی فن پارے کی زبان اور اسلوب کا مطالعہ جب لسانیات کی روشنی میں کیا جاتا ہے اور لسانیاتی طریقِ کار کی مدد لی جاتی ہے تو یہ مطالعہ ’اسلوبیات ‘ (Stylistics) کہلاتا ہے۔ اسی مطالعے کو ’اسلوبیاتی تنقید‘ بھی کہتے ہیں۔ اردو میں اس قسم کے مطالعے اور تجزیے کی بنیاد مسعود حسین خاں کے مضامین و مقالات سے پڑ چکی تھی جو انھوں نے امریکہ سے اپنی واپسی کے بعد گذشتہ صدی کی ساتویں دہائی کے اوائل سے لکھنا شروع کیے تھے۔ مغنی تبسم کو اسلوبیاتی تنقید سے دل چسپی مسعود حسین خاں ہی کی تربیت کی وجہ سے پیدا ہوئی اور انھی سے تحریک پاکر مغنی صاحب نے اردو میں اسلوبیاتی مضامین لکھے اور ا س کے اطلاقی و عملی نمونے پیش کیے۔
اسلوبیاتی تنقید سے مغنی تبسم کواس لیے بھی دل چسپی پیدا ہوئی کہ یہ ایک نیا اور روایتی ادبی تنقید سے حد درجہ مختلف نظریۂ تنقید تھا جس میں ادبی فن پارے کو خود کفیل و با اختیار مان کر اس کا معروضی و توضیحی مطالعہ و تجزیہ کیا جاتا تھا اور داخلی، تاثراتی اور تشریحی اندازِ نقد سے گریز کیا جاتا تھا۔ اسلوبیاتی تنقید کا یہ امتیاز انھیں پسند آیا اور انھوں نے چند برسوں کے دوران اردو میں اچھی خاصی تعداد میں اسلوبیاتی مضامین لکھ ڈالے جن میں سے بیشتر سیمیناروں میں پڑھے گئے اور مختلف رسائل میں شائع ہوئے۔ انھی مضامین کا مجموعہ مغنی صاحب نے کتابی شکل میں ’آواز اور آدمی‘( حیدرآباد: الیاس ٹریڈ رس، ۱۹۸۳ء) کے نام سے شائع کرایا۔
یہ کتاب گیارہ مضامین پر مشتمل ہے۔ شروع کے چار مضامین: ۱-’’اصوات اور شاعری‘‘، ۲-’’ قافیہ‘‘، ۳-’’غالب کا آہنگِ شعر اور بحروں کا استعمال‘‘، اور ۴- ’’غالب کی شاعری -بازیچۂ اصوات‘‘ خالص صوتیاتی نقطۂ نظر سے لکھے گئے ہیں۔ ان مضامین میں جو طریقِ کار اختیار کیا گیا ہے وہ خالصتہً معروضی اور تجزیاتی ہے۔ ان کے مطالعے سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ مغنی صاحب نہ صرف شعر کے رمز شناس تھے اور ادب کا رچا ہوا ذوق رکھتے تھے، بلکہ زبان کی ساخت اور اس کی توضیح پر بھی ان کی نظر بہت گہری تھی، نیز اردو کے صوتی و صرفی نظام کا بھی انھیں ٹھوس علم تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلوبیات جیسے موضوع پر صحیح معنیٰ میں وہی شخص قلم اٹھا سکتا ہے جو ادب اور زبان دونوں کی نزاکتوں سے بہ خوبی واقف ہو، اور لسانیات کے نظری اور اطلاقی پہلوؤں پرا س کی گرفت کا فی مضبوط ہو۔ مسعود حسین خاں سے کسبِ فیض کے دوران مغنی صاحب نے لسانیاتِ جدید کی مبادیات سے بھی کماحقہٗ واقفیت حاصل کر لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ادب کے اسلوبیاتی مطالعے اور تجزیے کے دوران انھیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔
شعری اسلوب کے صوتیاتی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے مغنی تبسم اپنے مضمون’’ اصوات اور شاعری‘‘ میں ایک جگہ لکھتے ہیں :’’یہ ایک حقیقت ہے کہ شعر کی خارجی موسیقی اصوات ہی کی مخصوص ترتیب سے تشکیل پاتی ہے۔ شاعر اصوات کے بامعنی مجموعوں کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور ہم ان آوازوں کو سن کر شعر سے متاثر ہوتے ہیں ‘‘(ص۱۰)۔ اسی مضمون میں مغنی صاحب نے اردو کے تمام مصوتوں (Vowels) اور مصمتوں (Consonants) کی تعریف و توضیح اور ان کی طرزِ ادائیگی، نیز مخارج کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی بھی پیش کی ہے۔ علاوہ ازیں ان کے صوتی وسماعی تاثر اور صوتی رمزیت وموسیقیت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اپنے مضمون ’’قافیہ‘‘ میں انھوں نے اردو قوافی کی صوتی بنیادوں کا پتا لگایا ہے اور ان کے صوتی تجزیہ و تحلیل سے بڑے دل چسپ نتائج اخذ کیے ہیں۔ اس مجموعے کا ایک اور اہم مضمون ’’غالب کا آہنگِ شعر اور بحروں کا استعمال‘‘ ہے جو بڑی دیدہ ریزی اور دقتِ نظر کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ یہ مضمون زبان کے حوالے سے ادبی تجزیہ و تحلیل کی نہایت عمدہ مثال پیش کرتا ہے۔ غالب کے آہنگِ شعر اور بحروں کے انتخاب واستعمال کے مطالعے اور تجزیے سے مغنی تبسم نے جو نتیجہ برآمد کیا ہے وہ یہ ہے کہ ’’غالب نے مختلف اوزان میں مصوتوں اور وقفوں کی تبدیلی سے آہنگ کے نت نئے تجربے کیے ہیں ‘‘( ص۷۲)۔
کلامِ غالب کے صوتیاتی تجزیے کے سلسلے کا ایک اور اہم مضمون ’’غالب کی شاعری – بازیچۂ اصوات‘‘ ہے جس میں مغنی صاحب نے غالب کی شاعری کے صوتی آہنگ کی تعمیر میں اصوات کی ترتیب و تنظیم اور تکرر(Frequency) کو اپنے مطالعے کا موضوع بنایا ہے، کیوں کہ ان کا خیال ہے کہ’’ غالب کے شعر کی تاثیر میں اس کے صوتی آہنگ کا جو حصہ ہے اسے نظر انداز کر دیں تو ہماری تحسین اور تنقید ادھوری رہ جائے گی‘‘ (ص ۷۵)۔ چنانچہ غالب کی شاعری کے صوتی تار و پود کا، جس سے ان کی شاعری کا لہجہ متعین ہوتا ہے اور شعر سے نغمے پھوٹتے ہیں، مغنی صاحب نے بڑی فنی مہارت، چابک دستی اور دقتِ نظر کے ساتھ مطالعہ پیش کیا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ’’غالب کی شاعری کے حسن اوراس کی تاثیر میں اصوات کے انتخاب اور ان کی تنظیم کو خاص دخل ہے۔ ۔ ۔ شعرِ غالب گنجینۂ معنی ہی نہیں بازیچۂ اصوات بھی ہے‘‘ (ص۷۶)۔
غالب پر اپنے ایک اور مضمون میں مغنی تبسم نے کلامِ غالب میں اسالیب کی آویزش کو اپنے مطالعے کا موضوع بنایا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق غالب کے یہاں دو اسالیب پائے جاتے ہیں — ایک خالص اردو اسلوب اور دوسرا فارسی آمیز اسلوب۔ یہ اسالیب ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ ایک مدت تک ان میں باہم کشمکش اور آویز ش جاری رہی اور آخر میں فارسی اسلوب کے بہت سے عناصر زائل ہو گئے۔ فارسی اسلوب کے عناصرِ ترکیبی میں فارسی مصادر، فارسی حروف (Particles)، فارسی جمع اور فارسی تراکیب کو غالب نے خاص اہمیت دی ہے۔ بعض اشعار میں فارسی افعال و تراکیب اور فارسی صرف و نحو کے استعمال کو انھوں نے اس حد تک جائز قرار دیا ہے کہ ان کے اردو اشعار پر فارسی اشعار کا دھو کا ہونے لگتا ہے۔
متذکرہ کتاب کا ایک اور اہم مضمون ’’میر کا لہجہ‘‘ ہے جس میں میر کی شاعری کے چند نمایاں لہجوں، مثلاً خطاب و تخاطب اور خود کلامی وغیرہ کا اسلوبیاتی مطالعہ پیش کیا گیا ہے اور مثالیں دی گئی ہیں۔ اسی ضمن میں مغنی صاحب کے ایک اور مضمون ’’حسرت کی غزل گوئی کے چند پہلو‘‘ کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے جس میں انھوں نے حسرت کی شاعری کے صوتی آہنگ کو اپنے مطالعے اور تجزیے کا موضوع بنایا ہے۔
’آواز اور آدمی‘ کے بیشتر مضامین شاعری کے صوتیاتی تجزیوں پر مشتمل ہیں۔ صوتیات کے بعد اسلوبیاتی تجزیے کی دوسری سطح لفظیات ہے، چنانچہ مغنی تبسم نے لفظیات کے حوالے سے بھی اردو شاعری کا اسلوبیاتی مطالعہ و تجزیہ پیش کیا ہے۔ اس ضمن میں ان کا موقف یہ ہے کہ لفظ کو متن سے الگ کر کے کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا اور نہ انفرادی طور پر لفظ کو بحث کا موضوع بنایا جا سکتا ہے، کیوں کہ یہ عین ممکن ہے کہ کسی شاعر کے یہاں الفاظ تو نئے ہوں، لیکن مضمون روایتی اور فرسودہ ہو۔ اس کے علی الرغم کوئی دوسرا شاعر قدیم الفاظ کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی نئے تجربے کا اظہار کر سکتا ہے۔
مغنی صاحب نے جدید غزل کی فرہنگِ شعر کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جدید غزل میں بہت سے الفاظ اور استعارے وہی استعمال ہوئے ہیں جو قدیم شاعری میں مروج تھے، لیکن ان کے استعمال کے پیرایے اور ان کے تلازمات بدل گئے ہیں۔ تاہم انھوں نے ایسے الفاظ کی ایک نامکمل فہرست پیش کی ہے جو قدیم غزل میں مستعمل تھے لیکن جدید غزل نے انھیں متروک قرار دے دیا، مثلاً لب، رخسار، گیسو، زلف، غمزہ، ادا، ناز، حیا، جفا، مسیحا، بیمار، دوا، دامن، گریبان، جنوں، بام، خلوت، محمل، وغیرہ۔ انھوں نے جدید غزل سے ماخوذ الفاظ کی بھی ایک فہرست دی ہے جس میں سے چند الفاظ یہاں نقل کیے جاتے ہیں، مثلاًسمندر، دریا، ندی، پانی، موج، ریت، ساحل، بادبان، پتوار، بارش، بادل، دشت، جنگل، صحرا، درخت، شجر، سورج، دھوپ، سایہ، دن، شام، رات، شب، تاریکی، اندھیرا، نیند، خواب، سناٹا، ہوا، گرد، تنہائی، آئینہ، عکس، چہرہ، مکان، دیوار، دریچہ، وغیرہ۔
اس کتاب کے دو اور مضامین ’’محمد علوی- گھر اور جدید غزل‘‘، اور’’ آئینہ- اردو غزل کا ایک مقبول استعارہ‘‘ بھی اسلوبیاتی نقطۂ نظر سے نہایت اہم ہیں۔ ان مضامین میں مغنی تبسم نے ’’گھر‘‘ اور ’’آئینہ‘‘ کے رموزو علائم اور ان کے تلازمات کا بڑی ژرف بینی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ یہاں بھی ان کا انداز تجزیاتی اور مشاہداتی ہے نہ کہ تاثراتی اور وجدانی۔ لفظ ’’گھر ‘‘ کی استعاراتی اور علامتی حیثیتوں سے بحث کرتے ہوئے مغنی تبسم لکھتے ہیں کہ یہ ’’ اپنے تکرر کی وجہ سے محمد علوی کی فرہنگِ غزل کا ایک مانوس اور مخصوص جزو بن گیا ہے، اور جس شعر میں بھی استعمال ہوا ہے بالعموم کلیدی لفظ بن کر آیا ہے‘‘( ص۱۰۱)۔ انھوں نے محمد علوی کے کئی اشعار پیش کر کے اپنی یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچا دی ہے۔ کلاسیکی شاعروں نے گھر کی ویرانی اور تباہی کا ذکر اکثر کیا ہے، لیکن ’’گھر‘‘ کا یہ قدیم تلازمہ ہے۔ محمد علوی نے اس لفظ کو عصری مسائل اور عصری حسیت سے جوڑ کر ایک نئے علامتی رنگ میں پیش کیا ہے۔ ان کا یہ شعر دیکھیے ؎
مجھے یہ دکھ ہے کہ میں نے یہ گھر بنایا کیوں
یہ گھر ہے آگ کی لپٹوں میں اور میں گھر میں ہوں
سہلِ ممتنع کی صفت سے متصف محمد علوی کایہ شعر بھی دیکھیے ؎
ابھی میں گھر کے اندر سورہا تھا
ابھی میں گھر سے بے گھر ہو گیا ہوں
مغنی تبسم لکھتے ہیں کہ ’’یہ شعر احمد آباد کے فرقہ وارانہ فسادات سے ذہنی طو ر پر متاثر ہو کر نہیں، بلکہ اس تجربے سے گذر کر لکھا گیا ہے۔ یہ ایک افتاد اور واردات کا راست اظہار ہے‘‘ (ص۱۱۱)۔
مغنی صاحب اپنے مضمون ’’آئینہ- اردو غزل کا ایک مقبول استعارہ‘‘ میں لکھتے ہیں کہ ’’آئینہ اردو غزل کا ایک سدا بہار استعارہ ہے۔ اس کے تشبیہی اور تلازماتی سوتے ہنوز خشک نہیں ہوئے ہیں ‘‘(ص۱۸۹)۔ اس بیان کے ثبوت میں انھوں نے ولیؔ دکنی سے لے کر پروین شاکر اور کشور ناہید تک بے شمار شعرا کے کلام سے’’آئینہ‘‘ کی مثالیں پیش کی ہیں۔ کسی نے اسے صفائی اور آب کے وصف سے متصف بتایا ہے تو کسی نے دل کو آئینے سے تشبیہ دی ہے، کسی نے آئینے سے آنکھ کی مماثلت ظاہر کی ہے تو کسی نے اسے چشمِ حیراں بتایا ہے۔ مغنی صاحب کا خیال ہے کہ ’’آئینہ غالبؔ کاسب سے مرغوب استعارہ ہے۔ آئینے کے جتنے تلازمے غالبؔ نے باندھے ہیں اور اس استعارے کے ذریعے جو جو معنی آفرینیاں غالبؔ نے کی ہیں اس کی مثال ساری اردو شاعری میں نہیں ملتی‘‘ (ص ۱۹۲)۔ ’’آئینہ ‘‘ جدید اردو شاعری میں بھی جلوہ فگن ہے۔ مغنی صاحب کہتے ہیں کہ ’’آئینے کا جو وصف جدید شاعری کی توجہ کو خاص طور پر کھینچتا ہے وہ اس کی بے رحم حقیقت بیانی ہے‘‘ (ص۱۹۶)۔ مثال کے طور پر کشور ناہید کا یہ شعر دیکھیے ؎
چھپاکے رکھ دیا پھر آگہی کے شیشے کو
اس آئینے میں تو چہرے بگڑتے جاتے تھے
’آواز اور آدمی ‘ میں ایک مضمون بہ عنوان ’’اقبال اور غزل ‘‘ بھی شامل ہے جو اس کتاب کے دیگر مشمولات سے میل نہیں کھاتا۔ چوں کہ یہ کتاب اسلوبیاتی مضامین کے لیے مختص ہے، اس لیے متذکرہ مضمون کو کسی دوسرے مجموعے میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ تاہم مغنی صاحب کا یہ ایک اہم تنقیدی مضمون ہے جس میں انھوں نے اقبال کے ابتدائی دور کے کلام پر داغ کا رنگ دکھلایا ہے اور اس کے بعد کی شاعری پر حالی کے اثرات کی نشان دہی کی ہے۔
بہ حیثیتِ مجموعی یہ کتاب مغنی تبسم کے اسلوبیاتی نظریۂ تنقید اور سائنسی طرزِ نقد کی نہ صرف بہترین عکاسی کرتی ہے، بلکہ ادبی تنقید کی ایک نئی جہت بھی متعین کرتی ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کے بنیاد گزاروں میں مغنی صاحب کا نام ہمیشہ لیا جاتا رہے گا۔
٭٭٭
ساختیاتی وپس ساختیاتی فکریات اور گوپی چند نارنگ
اردو میں گذشتہ تین دہائیوں سے ساختیاتی وپس ساختیاتی مباحث کا سلسلہ جاری ہے، اور جن دانشوروں اور نقادوں نے ان مباحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے ان میں پروفیسر گوپی چند نارنگ کا نام سرِ فہرست ہے۔ پروفیسر نارنگ اردو میں اسلوبیاتی نقاد کی حیثیت سے اپنا لوہا پہلے ہی منوا چکے ہیں۔ ان کی زیرِ نظر تصنیف ’ساختیات، پس سا ختیات اور مشرقی شعریات‘ (دہلی : ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، ۱۹۹۳ء) کی اشاعت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ساختیاتی مفکر و نقاد کی حیثیت سے بھی ان کا مرتبہ نہایت بلند ہے۔ اس کتاب کی اشاعت سے بہت پہلے سے وہ اس موضوع پر لکھتے رہے ہیں اور ساختیاتی وپس ساختیاتی فکریات کو اردو داں طبقے سے متعارف کرانے میں ہمیشہ پیش پیش رہے ہیں۔ اسلوبیات سے ساختیات تک کا سفرانھوں نے کچھ یوں ہی طے نہیں کیا ہے، بلکہ ادب، تنقید، لسانیات، معنیات اور نشانیات (Semiotics) سے گہرا شغف رکھنے کے ساتھ ساتھ انھوں نے نئی ادبی تھیوری کا بھی نہایت غائر مطالعہ کیا ہے۔ ہمارے ادبی نقاد مغربی مفکرین سے پہلے بھی استفادہ کرتے رہے ہیں، لیکن نئی ادبی تھیوری، بالخصوص ساختیات و پس ساختیات کے حوالے سے گوپی چند نارنگ نے اردو کی ادبی تنقید کو جو نیا موڑ دیا ہے وہ کوئی دوسرا نقاد نہیں دے سکا۔ اسی لیے اگر متذکرہ تصنیف کو ادبی تنقید کا ایک تاریخ ساز کارنامہ کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا۔
اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ’ساختیات‘ کا لسانیات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ساختی لسانیات (Structural Linguistics) کا ارتقا فرڈی نینڈ ڈی سسیلور (۱۸۵۷ تا ۱۹۱۳ء) سے ہوتا ہے۔ جس طرح سسیور کو لسانیاتِ جدید یا ساختی لسانیات کا ابو الآبا تسلیم کیا گیا ہے، اسی طرح ساختیاتی فکر کا بھی اسے امام مانا گیا ہے۔ گوپی چند نارنگ نے بجا طور پر اپنی اِس کتاب میں یہ تسلیم کیا ہے کہ ’’ساختیات کے بنیادی اصول سسیور کے خیالات پر مبنی لسانیات سے ماخوذ ہیں ‘‘ (ص ۵۹)۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ’’ساختیاتی فکر کا سر چشمہ بہر حال لسانیاتی ماڈل ہے جس نے اپنی ترغیباتِ ذہنی بنیادی طور پر سوِس ماہرِ لسانیات سسیور۔ ۔ ۔ سے حاصل کیں ‘‘ (ص ۳۸)۔ یہ بات بدیہی ہے کہ ساختیات پر گفتگو کرتے وقت فرڈی نینڈڈی سسیور کے لسانیاتی افکار یا اس کے فلسفۂ لسان سے صرفِ نظر نہیں کیا جا سکتا۔ سسیور کی کتاب نے، جو فرانسیسی زبان میں Course de Linguistique Generaleکے نام سے اس کی وفات کے تین سال بعد ۱۹۱۶ء میں شائع ہوئی (جس کا انگریزی میں ترجمہ ویڈبیسکن نے Course in General Linguistics کے نام سے کیا)، لسانیات کی دنیا میں ایک انقلابِ عظیم برپا کر دیا۔ ساختیاتی فکر کی بیش تر بنیادی باتیں سسیور کی اسی کتاب سے ماخوذ ہیں۔
بیسویں صدی کے وسط میں فرانس میں باقاعدہ طور پر ساختیات کا ارتقا عمل میں آیا، اس سے پھر پس ساختیات کے سوتے پھوٹے اور رد تشکیلی نظریے کو فروغ حاصل ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خواہ وہ ساختیات ہو یا پس ساختیات یا نظریۂ ردِ تشکیل، فرانسیسی مفکرین ہی ان کے فروغ میں پیش پیش رہے ہیں۔ چنانچہ ان نظریات کا ذکر رولاں بارت، ژاک لاکاں، مشل فوکو، ژاک دریدا اور جولیا کر سیٹوا کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ گوپی چند نارنگ نے اپنی متذکرہ کتاب میں ان مفکرین پر الگ الگ باب قائم کیے ہیں اور بڑی جامعیت اور علمی بصیرت کے ساتھ ان کی فکریات سے بحث کی ہے۔
پروفیسر نارنگ کی قابلِ قدر زیرِ نظر تصنیف ’ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات ‘ تین حصوں میں منقسم ہے۔ ہر حصے کو ’کتاب ‘ کا نام دیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلی کتاب ’’ساختیات‘‘، دوسری کتاب ’’پس ساختیات ‘‘ اور تیسری کتاب ’’مشرقی شعریات اور ساختیاتی فکر‘‘ کے نام سے موسوم کی گئی ہے۔ ہر حصے یا ’کتاب‘ میں کئی کئی ابواب شامل کیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ یعنی کتاب۔ اجسے ’’ساختیات‘‘ کا نام دیا گیا ہے پانچ ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے باب میں ساختیات اور ادب کے حوالے سے چند ابتدائی باتیں کہی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ عام ادبی نظریات کو ساختیات نے کس طرح چیلنج کیا ہے، اور کس طرح ایک ذہنی تحریک کے طور پر ساختیات کا ارتقا عمل میں آیا ہے۔ کتاب -۱ کے دوسرے باب میں ساختیات کی لسانیاتی بنیادوں سے بحث کی گئی ہے اور سسیور کے فلسفۂ لسان سے ساختیات کا رشتہ استوار کیا گیا ہے۔ ساختیات کے فروغ میں روسی ہیئت پسندوں (Russian Formalists) کے افکار و خیالات کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ روسی ہیئت پسندی پر ایک علاحدہ باب قائم کر کے ان کے نظریات سے مفصل بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب-۱ کا تیسرا باب ہے جس میں رومن جیکب سن، شکلوو سکی، بورس توما شیوسکی، وغیرہ کے حوالوں سے شعری زبان، ادب کی ادبیت (Literariness) اور ادب کے معروضی و تجزیاتی، نیز سائنٹفک مطالعے سے متعلق باتیں کہی گئی ہیں۔ اسی باب میں روسی ہیئت پسندوں کی فکشن کی شعریات کا بھی ذکر آگیا ہے۔
کتاب -۱ کا چوتھا باب فکشن کی شعریات اور ساختیات سے متعلق ہے جس میں فکشن کی شعریات کا رشتہ ساختیات سے استوار کیا گیا ہے اور ولادمیر پروپ، لیوی اسٹراس، نارتھروپ فرائی، گریما، تو دو روف اور ژنیت جیسے مفکرین کے حوالوں سے بات آگے بڑھائی گئی ہے۔ گوپی چند نارنگ کایہ خیال بجا ہے کہ ساختیاتی طریقِ کار بیانیہ (Narrative) کے مطالعے کے لیے خاص طور پر موزوں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساختیات کا اطلاق سب سے زیادہ بیانیہ ہی پر ہوا ہے۔ بیانیہ فکشن کا ایک وسیع میدان ہے جس میں مِتھ، اساطیر یا دیومالا، نیز کتھا کہانی اور لوک روایتوں سے لے کر ناول، افسانہ، ڈرامہ اور ایپک (Epic) تک شامل ہے۔ بقول نارنگ فکشن کی ان تمام اصناف کا ساختیاتی مطالعہ بہ خوبی کیا جا سکتا ہے۔ ولادمیر پروپ نے جوروسی ہیئت پسندتھا، روسی لوک کہانیوں کا ساختیاتی مطالعہ پیش کیا جس کے بارے میں نارنگ لکھتے ہیں کہ ’’پروپ نے جس طرح روسی لوک کہانیوں کے فارم کی گرہیں کھولیں اور ان کی ساختوں کو بے نقاب کیا، اس نے آگے چل کر بیانیہ کے ساختیاتی مطالعے کے لیے ایک روشن مثال کا کام کیا‘‘ (ص۱۰۷)۔ فرانسیسی ماہرِ بشریات لیوی اسٹراس نے فرانسیسی لوک کہانیوں کے فارم کو دیکھنے کے بجائے ان کی اصل (Roots)کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ چنانچہ نارنگ اس کے اِس قول سے متفق نظر آتے ہیں کہ ’’کسی بھی ثقافت کی جڑیں اس کی متھوں میں دیکھی جا سکتی ہیں ‘‘ (ص ۱۱۴)۔ فکشن کی شعریات کے حوالے سے ساختیاتی فکر کو آگے بڑھانے والوں میں نارتھروپ فرائی کا نام خصوصیت کے ساتھ قابلِ ذکر ہے، چنانچہ نارنگ نے اس کی تصنیف Anatomy of Criticism (1957)کے حوالے سے اس کے تنقیدی نظریات سے بڑی مدلل بحث کی ہے اور اس نے ادب کی شعریات کا نظام وضع کرنے کی جو کوشش کی تھی اسے ہر اعتبار سے’’حوصلہ مند اور قابلِ قدر‘‘ بتایا ہے۔ فکشن کی شعریات سے مزید سیر حاصل بحث کرتے ہوئے نارنگ نے اس باب میں گریما، تودو روف اور ژنیت کے افکار و نظریات کا بھی اسی طرح تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔
کتاب- ۱ کا پانچواں اور آخری باب ’’شعریات اور ساختیات‘‘ ہے جس میں گوپی چندر نارنگ نے رومن جیکب سن، اور جو نتھن کلر کے فکری حوالوں سے ساختیاتی شعریات سے بحث کی ہے۔ انھوں نے رومن جیکب سن کو، جو فرڈی نینڈ ڈی سسیورسے گہرے طور پر متاثر تھا، ساختیاتی شعریات کے بنیاد گزاروں میں شمار کیا ہے۔ جیکب سن نے سسیور کے لسانی تصورات کے شعریات پر اطلاق ہی سے ہی ساختیات شعریاتی کی تشکیل کی۔ سسیورنے زبان کے افقی(Syntagmatic) اور عمودی (Paradigmatic) رشتوں کا تصور پیش کیا تھا۔ جیکب سن نے اس تصور کو نہ صرف ساختیاتی شعریات کے بنیادی اصول کے طور پر برتا، بلکہ اس میں توسیع پیدا کی۔ اب یہ تصور بعض انسانی رویوں اور ثقافتی نظام کو بھی سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔
زیرِ نظر کتاب کے دوسرے حصے کو کتاب-۲کا نام دیا گیا ہے اور اس کا عنوان ’’پس ساختیات ‘‘رکھا گیا ہے۔ یہ حصہ چھے ابواب پر مشتمل ہے۔ اس حصے یعنی کتاب-۲ کے پہلے باب میں پس ساختیاتی فکر سے مفصل بحث کی گئی ہے جس کا وجود ساختیات سے ’’گریز‘‘ کے طور پر ساتویں دہائی کے اواخر میں عمل میں آیا۔ گوپی چند نارنگ نے بجا طور پر فرانسیسی مفکر اور نظریہ ساز رولاں بارت کو پس ساختیات کا’’ پیش رو‘‘ قرار دیا ہے۔ اُس کی اس فکر ک ے پیچھے جوفلسفیانہ بصیرت کام کر رہی ہے اور اس نظریے کی تشکیل میں جو نشانیاتی (Semiological) ادراک شامل ہے اس کو سمجھے بغیر رولاں بارت کے پس ساختیاتی تصورِ ادب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ نارنگ نے اس باب میں رولاں بارت کے پس ساختیاتی نظامِ فکر کی تمام بنیادی باتوں کا بڑی خوبی کے ساتھ احاطہ کیا ہے اور جا بہ جا اس کی تصانیف کے حوالے اورقتباسات پیش کیے ہیں۔ وہ رولاں بارت کو فرانس کے ساختیاتی مفکروں اور نقادوں میں ’’سب سے زیادہ دل چسپ، نکتہ رس اور بے باک‘‘ نظریہ ساز قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ’’زبان و ادب اور ثقافت کے بارے میں روایتی تصورات کی بت شکنی اس کی سرشت کا حصہ تھی، اور اس میں وہ ایسی لذت محسوس کرتا تھا جو اکثر اوقات تخلیق کی اعلیٰ ترین حدوں کو چھو لیتی ہے‘‘ (ص ۱۵۹)۔ رولاں بارت کی فکر سے بحث کرتے ہوئے نارنگ نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ وہ معنی کی وحدت یا متعینہ معنی کے سخت خلاف تھا۔ اس کا سارا زور معنی خیزی(Signification)پرتھا، محض معنی پر نہیں۔ وہ زبان کو صاف ستھرایاشفاف میڈیم تصور نہیں کرتا تھا۔ اس کے خیال میں زبان جو ادب کا میڈیم ہے، اس میں معنی کی اتنی پرتیں ہوتی ہیں کہ کوئی بھی ادیب اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے ذریعے وہ سچائی یا حقیقت کو جوں کاتوں بیان کر سکتا ہے۔ اسی لیے نارنگ نے ’کثیرالمعنیت‘ کو رولاں بارت کی فکر میں بنیادی حیثیت دی ہے۔ وہ رولاں بارت کو فرانس کے ساختیاتی ادبی نقادوں میں سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ’’موجودہ عہد میں ادب کے بارے میں کسی مفکر نے اتنی بحثیں نہیں اٹھائیں جتنی رولاں بارت نے‘‘(ص۱۶۰)۔
رولاں بارت کے بعد پس ساختیاتی فکر کو فروغ دینے والوں میں ژاک لاکاں، مشل فوکو، جولیا کرسیٹوا اور ژاک دریدا کے نام خصوصیت کے ساتھ قابلِ ذکر ہیں۔ چنانچہ گوپی چند نارنگ نے کتاب۔ ۲کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے باب میں ان پس ساختیاتی مفکرین کے خیالات اور ان کے علمی کارناموں سے مفصل بحث کی ہے۔ دوسرے باب میں ژاک لاکاں، مشل فوکو اور جولیا کرسیٹوا کاذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ تیسراباب ژاک دریدا کے لیے مختص ہے اور چوتھے باب میں اس کے نظریۂ ردِ تشکیل کو بحث کا موضوع بنایا گیا ہے۔
پس ساختیاتی مفکرین میں ژاک لاکاں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ، لیکن وہ فلسفی کے بجائے، تربیت کے لحاظ، سے ماہرِ تحلیلِ نفسی(Psychoanalyst)اور ذہنی امراض کا ماہر(Psychiatrist)تھا۔ لاکاں نے فرائیڈ کی ’تحلیلِ نفسی‘ کو نئی معنویت دی اور ’فرائیڈیت‘(Friedism) کی نئی قرأت پیش کر کے اسے یکسر بدل دیاجسے لاکاں کی نوفرائیڈیت‘ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سے ادب کی افہام و تفہیم میں دور رس نتائج مرتب ہوئے۔ لاکاں نے فرائیڈ کے نظریۂ شعور سے بھی بحث کی اور کہا ہے کہ فرائیڈ نے نہ صرف لاشعور کو دریافت کیا اور اس کے وجود کو ثابت کر دکھایا، بلکہ یہ نظریہ بھی پیش کیا کہ لاشعور ’ساخت‘ رکھتا ہے۔ نارنگ کا خیال ہے کہ یہ ساخت ہمارے اعمال و افعال کو اس طور پر متاثر کرتی ہے کہ اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے‘‘(ص ۱۸۳)۔ مشل فوکو کی حیثیت ایک فلسفی کی ہے جس نے پس ساختیاتی نظریے کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ فوکو اپنے نظریۂ ’متینت‘ (Textuality) اور’ڈسکورس‘ (Discourse)کے لیے مشہور ہوا۔ ان اصطلاحات کا استعمال اس کے یہاں خالص فلسفیانہ انداز میں ہوا ہے جس کا سمجھنا خاصا مشکل کام ہے۔ نارنگ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ’’ فوکو اپنے نظریۂ ڈسکورس کے ذریعے جرمن فلسفی نطشے کی نئی تعبیر پیش کر رہا ہے‘‘(ص ۱۹۴)۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ’’فوکو ڈسکورس کو ذہنِ انسانی کی مرکزی سرگرمی قرار دیتا ہے، ایک عام آفاقی متن کے طور پر نہیں بلکہ ’معنی خیزی‘ کے ایک وسیع سمندر کے طور پر‘‘(ص۱۵۹)۔ جولیا کرسٹیوابھی پس ساختیاتی مفکرین میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ اس کا اصل میدان ادب و تنقید بالخصوص و ادبی معنیات‘ ہے۔ اس نے شعری زبان کا اپنا ایک نظریہ بھی پیش کیا ہے جو تحلیلِ نفسی پر مبنی ہے۔ نارنگ اس کے نظریے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ’’ وہ ان ذہنی رویوں کا سراغ لگانا چاہتی ہے جن کے باعث ہر وہ چیز جو معقول اور منظم سمجھی جاتی ہے، غیر معقولیت اور انتشار کے خطرے سے دو چار رہتی ہے‘‘(ص۲۰۰) نارنگ نے جولیا کرسیٹوا کے شعری زبان کے تصور اور شاعری میں آوازوں کے زیر و بم اور آہنگ کے بارے میں اس کے خیالات سے بھی دلائل کے ساتھ بحث کی ہے۔
گوپی چند نارنگ نے کتاب-۲کا تیسرا اور چوتھا باب ممتاز پس ساختیاتی مفکر ژاک دریدا اور اس کے نظریۂ ردِ تشکیل کے لیے مختص کیا ہے۔ فوکو کی طرح دریدا بھی ایک فلسفی تھا جس نے ردِ تشکیل کا نظریہ پیش کر کے پس ساختیاتی فکر کو ایک نئی جلا بخشی اور ایک نئی جہت سے روشناس کرایا۔ دریدا متن(Text)کے متعینہ معنی کو تسلیم نہیں کرتا تھا اور معنیاتی وحدت کے خلاف تھا۔ متن کے متعینہ معنی کی اسی بے دخلی کو وہ وردِ تشکیل‘ (Deconstruction)سے تعبیر کرتا ہے۔ پس ساختیاتی تنقید میں ردِ تشکیل کی مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں جو بے حد پیچیدہ ہیں، لیکن نارنگ نے اس کی جو تعریف پیش کی ہے وہ نہایت سادہ اور عام فہم ہے۔ ان کے نزدیک ’’ردِ تشکیل سے مراد متن کے مطالعے کا وہ طریقۂ کار ہے جس کے ذریعے نہ صرف متن کے متعینہ معنی کو بے دخل(Undo) کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کی معنیاتی وحدت کو پارہ پارہ بھی کیا جا سکتا ہے‘‘(ص۲۰۴)۔ نارنگ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ رد تشکیلی طریقۂ کار کا رواج پہلے پہل فرانس کے Tel Quelگروپ کے لکھنے والوں میں ہوا، لیکن اس کو فلسفیانہ طور پر دریدا نے ہی قائم کیا، اور اب یہ اسی سے منسوب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رد تشکیلی نظریے کا ’’بنیادی سروکار‘‘ معنی ہی سے ہے، لیکن یہ نظریہ اس بات پر، بقول نارنگ، سختی سے زور دیتا ہے کہ ’’زبان کی ساخت اس نوع کی ہے کہ معنی کی حتمیت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ معنی ہمیشہ عدم قطعیت کا شکار ہے‘‘(ص۲۲۱)۔
کتاب-۲ کے پانچویں باب کا عنوان ’’مارکسیت، ساختیات اورپس ساختیات‘‘ ہے۔ اس باب میں پانچ مارکسی دانشوروں اور نظریہ سازوں کے افکار و خیالات سے بحث کی گئی ہے جن کے نام ہیں : لوسی این گولڈ من (رومانیہ)، پیئرماشیرے (فرانس)، لوئی آلتھیوسے (فرانس)، ٹیری ایگلٹن(برطانیہ)، اور فریڈرک جیمس(امریکہ)۔ ان مفکرین کے فکری رویوں میں گوپی چند نارنگ نے مارکسیت اور ساختیات وپس ساخیتات کا اشتراک تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ مفکرین ہیں جنھوں نے ادبی تنقید کو گہرے طور پر متاثر کیا ہے۔
کتاب-۲ کا چھٹا باب ’’قاری اساس تنقید‘‘ ہے جس میں ’قاری اساس تنقید‘ (Reader – Response Criticism)کے آغاز و ارتقا اور موقف سے بحث کی گئی ہے۔ یہ تنقید ساتویں دہائی کے اواخر میں شروع ہوئی جسے گوپی چند نارنگ ’’انقلابی تنقیدی قوت‘‘ قرار دیتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ’’ یہ تنقید مصنف کے جبر کو رد کرتے ہوئے۔ ۔ ۔ معنی کی بوقلمونی کی تعبیر و تشکیل میں قاری کو شریک کرتی ہے‘‘ (ص ۲۷۱)۔ انھوں نے آئی۔ اے۔ رچرڈز اور نار تھروپ فرائی کو قاری اساس تنقید کا پیش روتسلیم کیا ہے۔ اسی باب میں انھوں نے تفہیمیت(Hermeneutics) اور مظہریت (Phenomenology) سے بھی بحث کی ہے۔ تفہیمیت کو وہ صدیوں پرانا فلسفہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف ادبی مطالعے سے نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی خاص طریقۂ کار اور ضابطۂ عمل ہے جس کی پابندی ضروری ہو۔ ان کا یہ خیال بجا ہے کہ’’ تفہیمیت کا آغاز قدیم متون کو پرکھنے اور ان کے حقیقی معنی جاننے کے لیے ہوا تھا، آج اسے مختلف علوم میں تفہیم کاری کے کام کے لیے برتا جاتا ہے، اور اس کا چلن مذہبیات کے علاوہ تاریخ، سماجیات، قانون اور علوم انسانیہ کے مختلف شعبوں میں ہو رہا ہے‘‘(ص ۲۸۷)۔ مظہریت کے سلسلے میں نارنگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک فلسفیانہ رویہ ہے جسے جرمن فلسفی ایڈمنڈ ہوسرل نے قائم کیا۔ مظہریت کا انسانی شعور سے گہرا تعلق ہے، چنانچہ ہوسرل کا یہ خیال توجہ طلب ہے کہ جو مظاہر (Phenomena) ہمارے شعور میں ہیں، انھی کے ذریعے ہم اشیاء کی اصل اور ان کی صفات کا تعین کرتے ہیں (بہ حوالہ نارنگ، ص ۲۹۴)مظہریت کو تنقیدی رویے کے طور پر بھی برتا جاتا ہے، چنانچہ نارنگ کہتے ہیں کہ’’ مظہریاتی تنقید کے نزدیک ادب شعور کی ایک فارم ہے، اور تنقید کا کام اس فارم کا تجزیہ کرنا ہے اور اس میں مصنف کے تہ نشین شعور کی نشان دہی کرنا ہے‘‘(ص ۲۹۴)۔
زیرِ نظر کتاب کے تیسرے حصے یعنی کتاب۔ ۳میں گوپی چند نارنگ نے ’’مشرقی شعریات اور ساختیاتی فکر‘‘ سے بحث کی ہے۔ کتاب کا یہ حصہ بھی پچھلے دو حصوں کی طرح بڑی۔ دو ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے باب میں سنسکرت شعریات اور دوسرے باب میں عربی فارسی شعریات کا نہایت مفصل اور عالمانہ محاکمہ کیا گیا ہے۔ نارنگ نے سنسکرت شعریات کی صدیوں کی روایت کا ساختیاتی فکر کی روشنی میں ازسر نو جائزہ لیا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ’’مغرب میں جو نکات اب ساختیاتی وپس ساختیاتی اور رد تشکیل فکر کے تحت بیان کیے جا رہے ہیں ان سے ملتے جلتے نکات ہندوستانی فکر وفلسفے بالخصوص بودھ فلسفے میں صدیوں پہلے زیرِ غور رہے ہیں ‘‘ (ص ۳۳۸)۔ انھوں نے بودھی نظریۂ اپوہ نیز شونیہ، سپھوٹ اور دھونی سے متعلق نظریات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور ان نظریات میں اورساختیاتی وپس ساخیتاتی فکر اور نظریۂ رد تشکیل میں اشتراک اور مماثلتوں کی نشان دہی کی ہے جو بلاشبہ لائقِ داد وتحسین ہے۔ اسی طرح انھوں نے اس حصۂ کتاب میں عربی فارسی شعریات سے بھی اپنی گہری واقفیت کا ثبوت فراہم کیا ہے اور یہ خیال پیش کیا ہے کہ ’’مشرق میں لسان و لغت اور بیان و بلاغت پر غور فکر کی جو قدیم روایات رہی ہیں ان میں بعض ایسے نکات بھی ہیں جو جدید فلسفۂ لسان یاساختیات کے پیش رو معلوم ہوتے ہیں، بھلے ہی ان کی منطقی تحلیل اس درجہ نہ کی گئی ہو‘‘(ص۴۸۶)۔
گوپی چند نارنگ نے ’’صورتِ حال‘ مسائل اور امکانات‘‘ کے عنوان سے زیرِ نظر کتاب کا ’اختتامیہ‘ بھی تحریر کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تھیوری یعنی نظریہ سازی پر اتنی توجہ کیوں صرف کی گئی ہے۔ پس ساختیاتی فکر کے اہم نکات کو پھر سے بیان کیا گیا ہے یا ان کی تلخیص پیش کی گئی ہے۔ دریدا اور مارکسیت پر بھی اظہارِ خیال کیا گیا ہے۔ رولاں بارت، لاکاں، فوکو، جولیا کرسیٹوا، آلتھیوسے، ٹیری ایگلٹن، وغیرہ کے خیالات کا اعادہ کیا گیا ہے، اور دل چسپ بات یہ ہے کہ اسی اختتامیہ میں ’مابعد جدیدیت‘ کو متعارف کرایا گیا ہے جو ایک نئی ادبی صورتِ حال ہے اور جس کا ارتقا ہمارے یہاں جدیدیت کے ردِ عمل کے طور پر عمل میں آیا، لیکن مغرب میں صورتِ حال مختلف تھی۔ اختتامیہ کے آخر میں اردو تنقید کی موجود ہ صورتِ حال کو بھی بیان کیا گیا ہے جوان کے نزدیک زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔
تقریباً چھے سوصفحات پر مشتمل کتاب’ساختیات‘ پس ساختیات اور مشرقی شعریات‘ کی تسویدکے دوران پروفیسرگوپی چند نارنگ کا یہ طریقِ کار رہا ہے کہ صفحہ در صفحہ الگ الگ حوالے اور حواشی (References) دینے کے بجائے انھوں نے اس کتاب کے ہر حصے کے آخر میں ’ مصادر‘ کے تحت ہر باب سے متعلق ان تمام کتابوں کے نام (مصنفین و مرتبین کے ناموں اور ناشرین کے حوالوں نیز مقام وسنہِ اشاعت کے ساتھ) درج کر دیے ہیں جوا ن کے زیرِ مطالعہ رہی ہیں یا جن سے انھوں نے استفادہ کیا ہے۔ اس طرح متعلقہ موضوعات پر شائع شدہ تقریباً دوسو مستند کتابوں کی تفصیلات مہیا کرا دی گئی ہیں جو قارئین کے لیے کسی بیش قیمت علمی خزانے سے کم نہیں۔ پروفیسر نارنگ لائقِ مبارک باد ہیں کہ انھوں نے ایک ایسے موضوع پر قلم اٹھایا جسے اردو نے اپنی بے بضاعتی کے باعث اپنی پوری ادبی تاریخ کے دوران کبھی مس نہیں کیا تھا۔ وہ ساختیاتی، پس ساختیاتی اور رد تشکیلی نظریوں کے بنیاد گزار نہ سہی، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان معاصر تنقیدی رویوں اور فکری مباحث کو اردو میں متعارف کرانے کا سہرا انھی کے سر ہے اور یہ کام انھوں نے اپنی تمام تر علمی، ادبی، تنقیدی اور دانشورانہ صلاحیتوں کو بروئے عمل لاتے ہوئے بہ حسن و خوبی انجام دیا ہے۔ چوں کہ یہ نظریات اور فکری میلانات مغرب سے ہمارے یہاں آئے ہیں، اس لیے مغربی مصنفین و مفکرین کی تصانیف سے اخذواستفادہ ان کے لیے ناگزیر تھا، ورنہ اردو میں ایسی کتاب کے معرض وجود میں آنے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔
](’ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات‘]گوپی چند نارنگ[ پر راقم السطور کے تبصرے مطبوعہ ’ہماری زبان‘]نئی دہلی[، جلد شمارہ پر مبنی مضمون)
٭٭٭
دِوّیہ بانی – ایک دلت بیانیہ
ہندوستانی معاشرے کے دبے کچلے، پسے ہوئے اور پس ماندہ طبقے کے افراد آج ’دلت‘ کہے جاتے ہیں۔ گاندھی جی نے انھیں ’ہریجن‘ کا نام دیا تھا۔ سرکاری طور پر انھیں ’شیڈولڈ کاسٹ‘ کہا جانے لگا۔ دلت دراصل ہندوؤں کی نچلی ذات (Low-Caste) سے تعلق رکھنے والے وہ غریب، کم زور اور پچھڑے ہوئے لوگ وہ غریب، کم زور اور پچھڑے ہوئے لوگ ہیں جنھیں ہندو طبقۂ اشرافیہ نے سماجی، تہذیبی اور مذہبی سطح پر الگ تھلگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اونچی ذات کے ہندوؤں کے ذریعے دلتوں کا استعمال اور ان کی ذلت و خواری کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ سلسلہ ویدک عہد سے جاری ہے۔ ہندوؤں کی قدیم مقدس کتاب ’مانو دھرم شاستر‘ (جسے Laws of Manu) بھی کہتے ہیں ) کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ قدیم عہد میں ہندو معاشرے کے کی بنیاد ذات پات کی تفریق پر رکھی گئی تھی۔ اونچی ذات کے ہندوؤں یا طبقہ اشرافیہ میں برہمن، چھتری، اور ویش شامل کیے گئے تھے جنھیں اونچی ذات کے ہندوؤں کی خدمت گزاری پر مامور کیا گیا تھا۔ ان میں سے کسی کی بھی ذات تبدیل نہیں ہوسکتی تھی۔ ان کی آئندہ نسلوں کی ذات بھی وہی مانی جاتی تھی جو ان کے پورو جنوں یعنی آباء کی ذات ہوتی تھی۔ ان چار ذاتوں کے علاوہ ہندوؤں کا ایک اور طبقہ بھی تھا جسے ذات سے باہر (Quteaste) سمجھا جاتا تھا، اور یہ ’اچھوت ‘ کہلاتا تھا۔ انھیں ایسے ادنیٰ کام سونپے گئے تھے جنھیں سرانجام دنیا باعثِ عار ور موجب شرم و ذلت سمجھا جاتا تھا۔ یہی اچھوت اور شودر آج کے دلت ہیں۔ غضنفر کا ناول ’دِویہ بانی‘ (۲۰۰۰ء) اسی سماجی و تہذیبی تناظر میں لکھا گیا ہے۔
کئی جدید ہندوستانی زبانوں مثلاً مراٹھی، گجراتی، ہندی، تامل، تلگو، وغیرہ کے ادب میں دلتوں کے مسائل اور ان کی طرزِ زندگی پر خاصی توجہ دی گئی ہے، لیکن اردو میں پریم چند (۱۸۸۰ تا ۱۹۳۶ء) سے قبل دلتوں کی حالت کی جانب کسی ادیب کی توجہ مبذول نہیں ہوئی تھی۔ پریم چند غالباً پہلے اردو ادیب ہیں جنھوں نے اپنے ناول ’گوشۂ عافیت‘ (۱۹۲۰ء) میں کسانوں کے ساتھ دلتوں کے دکھ درد اور مسائل کو بھی حقیقی رنگ میں پیش کیا۔ انھوں نے اپنا آخری افسانہ ’’گفن‘‘ (۱۹۳۶ء) بھی دلت تناظر ہی میں لکھا اور گھیسو، مادھو اور بدھیا جیسے ناقابلِ فراموش کردار تخلیق کیے۔ پریم چند کے بعد ایک طویل عرصے تک اردو میں کسی اور نے اس موضوع پر قلم نہیں اٹھایا، لیکن مابعد جدیدیت کے فروغ پاتے ہی ادبی صورتِ حال یکسر تبدیل ہو گئی اور بعض اردو ادیبوں نے دلتوں کے مسائل پر بھی لکھنا شروع کیا جن میں ایک نمایاں نام غضنفر کا ہے۔ انھوں نے ’دِویہ بانی‘ لکھ کر اردو ناول نگاری میں ایک نئے اور اچھوتے موضوع کا اضافہ کیا ہے، لہٰذا ’دِویہ بانی‘ کو اگر اردو کا پہلا باقاعدہ دلت ناول کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا۔
(۲)
غضنفر نے ’دِویہ بانی‘ میں دلتوں کی زنگی اور ان کے رہین سہن کے طور طریقوں کی بہترین عکاسی کی ہے، اور ان کی ابتر سماجی حالت اور ان کے دکھ درد کو حقیقی رنگ میں پیش کیا ہے۔ اسی کے ساتھ انھوں نے نے دلتوں کا استحصال کرنے والوں کا بھی پردہ فاش کیا ہے۔ ’دِوّیہ بانی‘ کی قرأت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اونچی ذات کے ہندو (بالخصوص برہمن) دلتوں پر کیسے کیسے مظالم روا رکھتے ہیں۔ ذرا ذراسی بات پر انھیں کس بری طرح مارا پیٹا جاتا ہے۔ پوتربانی (مقدس کلام) دویہ بانی سننے پر ان کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا ہے جو ان کی قوتِ سماعت کو سلب کر دیتا ہے، اور انھیں اس بری طرح زد وکوب کیا جاتا ہے کہ جسم لہولہان ہو جاتا ہے۔ انھیں ’بھگوان‘ کا نام لینے سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ دلتوں کو ندی میں نہانا، جہاں اونچی ذات کے ہندو نہاتے ہیں، ورجِت (ممنوع) ہے۔ دلت مرد عورتوں کو گندے نالے کے پانی میں نہانا پڑتا ہے۔ دلت اونچی ذات کے ہندوؤں کے صاف ستھرے اور کشادہ رہائشی علاقے بامھن ٹولے سے دور ایک تنگ و تاریک گلیوں والی پرُ تعفن گندی بستی میں رہتے ہیں جو چمٹولی کہلاتی ہے۔ ان کے پھوس اور چھپر کے بنے مکان، دیواریں اور فرش دیکھ کر گھن آتی ہے۔ ان کے گھروں کی کیچڑ اور بدبو دار پانی سے بھری لبالب نالیوں میں کلبلاتے ہوئے کیڑوں کو دیکھ کر متلی آنے لگتی ہے، اور گھروں کے آس پاس کی گندگی، غلاظت، کوڑوں کے ڈھیر، گوبر اور مَل مؤتر (بول و براز) سے اٹھنے والی بدبو سے دماغ پراگندہ ہو اٹھتا ہے۔ دلتوں کے کھانوں کے برتن کتوں کے کھانے کے برتنوں جیسے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کھانا بھی دوسرا کے برتنوں جیسے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کھانا بھی دوسرا بنتا ہے۔ جو بھوجن (کھانا) اونچی ذات کے ہندو کھاتے ہیں وہ انھیں نہیں دیا جاتا ہے۔ دلت کٹھن پر شرم (سخت محنت) کرتے ہیں، کیوں کہ اونچی ذات کے ہندوؤں کے بہ قول ’’ایشور نے شَرم (محنت و مشقت ) انھی کو سوپنا ہے۔ ‘‘ گاؤں کی پاٹھ شالا میں گرو جی دویہ بانی سناتے ہیں، لیکن جو نچلی ذات کے ہندو ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ اونچی ذات کے ہندو کہتے ہیں کہ ’’جو ہم میں سے نہیں ہے اس نے دویہ بانی سنی تو ڈنڈ (سزا) کا بھاگی ہو گا۔ ‘‘ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ’’ہمارے اترکت (علاوہ) جو کوئی دویہ بانی سنے گا، اس پر دیوتا کا شراب (عذاب) پڑے گا۔ ‘‘
دلت مرد دبلے پتلے اور لاغر ہوتے ہیں جن کا اوپر سے نیچے تک رنگ میلا ہوتا ہے۔ دلت عورتیں بھی کالی کلوٹی ہوتی ہیں۔ ان کی ساڑی میلی چکٹ رہتی ہے۔ دلتوں کے بچے بھی دھول مٹی اور کیچڑ میں لت پت، گندے اور ننگ دھڑنگ رہتے ہیں۔ دلتوں کی غربت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے اور بھوک مٹانے کے لیے مرے ہوئے ڈانگر (جانور) کا سڑا ہوا مانس (گوشت) کھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ دلتوں کے بچے پاٹھ شالا نہیں جا سکتے، کیوں کہ وہاں دویہ بانی سنائی جاتی ہے جو ان کے لیے ورجت (ممنوع) ہے۔ دلت یہ سارے ظلم وستم اور ناانصافیاں برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن اُف تک نہیں کرتے، کیوں کہ انھیں اونچی ذات کے ہندوؤں (برہمنوں ) کے عتاب کا ڈر ہر وقت ستاتا رہتا ہے۔
غضنفر کا یہ ناول دلتوں اور برہمنوں کے درمیان روایتی تضادات اور سماجی نا برابریوں کو بہ خوبی اجاگر کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بامھن ٹولے کے ایک معزز برہمن خانوادے کے بزرگ، جنہیں لوگ ’بابا‘ کہتے ہیں، کی شخصیت کے تضاد اور کردار کے دوہرے پن کو بھی طشت از بام کرتا ہے۔ بابا بہ ظاہر مذہب کے ٹھیکے دار اور اخلاقی قدروں کے پاس دار ہیں، لیکن بہ باطن بہ طینت اور بدکردار۔ اس کا پردہ بالآخر فاش ہو جاتا ہے۔ ان تمام امور کے با وصف ’دِویہ بانی‘ برہمن زادے بالیشور اور ایک دلت کے پیٹ سے جنم لینے والی بندیا کے پیار کی کہانی بھی ہے جسے بیانیہ (Narrative) کی شکل دی گئی ہے۔
’دِوّیہ بانی‘ بیانیہ اسلوب میں لکھا ہوا ایک دلت ناول ہے۔ بیانیہ یا ادبی بیانیہ دراصل کہانی ہی کا دوسرا نام ہے جس میں کہانی ہی کی طرح پلاٹ، واقعات کا تسلسل اور کردار ہوتے ہیں۔ بیانیہ میں کہانی کی طرح کلائمکس (Climax) بھی ہوتا ہے۔ ایک مکمل بیانیہ میں بہ لحاظِ ترتیب تین حصے پائے جاتے ہیں یعنی، ابتدا-ارتقا-انتہا-انھیں ہم بیانیہ کی زمانی ترتیب بھی کہہ سکتے ہیں۔ بیانیہ کہانی تو ہوتا ہی ہے، کہانی کا کوئی حصہ بھی بیانیہ ہوسکتا ہے۔ بیانیہ میں مصنف یا ناول نگار خود راوی یا بیان کنندہ (Narrator) ہوتا ہے، لیکن اگر بیانیہ طویل ہے تو اس کا کوئی کردار بھی راوی بن سکتا ہے، مثلاً دانو اور دیوتا کے درمیان امرت حاصل کرنے کے لیے جو یدھ (جنگ) ہوا تھا اور جس میں دیوتاؤں کی جیت ہوئی تھی اس کا راوی اس یدھ کے ناٹک میں بھاگ (حصہ) لینے والا جاگیشور ہے جو اس ناول کا ایک کردار ہے۔ اسی طرح گاؤں کی ناٹک منڈلی میں کھیلے گئے ایک ناٹک میں برہما ایک کردار کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں اور اپنے سر، بازو، پیٹ، اور پیر سے انسانوں کی تخلیق کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں، ’’میں برہماہوں تم سب کا جنم داتا، مجھے پر نام کرو‘‘۔ اس کے بعد کے پورے منظر نامے کے راوی برہما ہی ہیں۔
ناول کا پلاٹ ذات پات کے بھید بھاؤ اور سماجی تفریق کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے جس میں ہندو دیومالائی عناصر کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اس میں رونما ہونے واقعات میں زمانی تسلسل ہے اور کرداروں کے فعل و عمل کے ذریعے بیانیہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ارتقا کی منزلیں طے کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔
(۳)
یہ ادبی بیانیہ جھگرو نامی ایک دلت پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کے بیان (Narration) سے شروع ہوتا ہے۔ جھگرو کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے دِویہ بانی سن لی تھی۔ اس جرم کی پاداش اسے اس حد تک مارا پیٹا جاتا ہے کہ اس کا جسم شدید طور پر زخمی ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا بھی ڈالا جاتا ہے۔ وہ ہَون کنڈ کے چبوترے کے نیچے پتھریلی زمین پر قربانی کے جانور کی طرح پچھاڑیں کھاتا ہے۔ ان مظالم کے ڈھانے والے بامھن ٹولے کے وہی بابا ہیں جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، اور جھگرو ان کاداس (ملازم) ہے۔ بابا اس دلت کو اذیت پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہَون کنڈ کے چبوترے پر بیٹھے پر سکون انداز میں ہَون کی کریا بھی پوری کرتے جاتے ہیں۔ اس جگر خراش ختط کو بابا کا پوتا بالک (بالیشور) بھی دیکھتا ہے۔ اس کے دل میں جھگرو سے ہم دری اور بابا کے خلاف شدید نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بابا سے اس واقعے سے متعلق طرح طرح کے سوالات کرتا ہے جن کے جواب سے وہ قاصر رہتے ہیں۔ جھگرو کا بیٹا بالو بھی اسی گھر میں ملازم ہے۔ وہ بالیشور کی دیکھ بھال پر مامور ہے۔ بابو اور بالیشور ہم عمر ہیں۔ ان دونوں میں دوستی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، لیکن بابا اسے پسند نہیں کرتے۔ ایک دن بالیشور بابو کے ساتھ جھگرو کو دیکھنے اس کے گھر (چمٹولی ) جاتا ہے جہاں کی غربت، غلاظت، گندگی، تعفن اور ابتر معاشی حالت کو دیکھ کہ اس کا دل بری طرح دکھتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہتا ہے کہ اس میں اور بالو یا جھگرو میں اتنا فرق کیوں ہے، چمٹولی کے لوگ اتنے گندے کیوں رہتے ہیں، اور ان کے بچے پاٹھ شالا کیوں نہیں جاتے، نیز بالو اور اس کے گھر والے دِویہ بانی کیوں نہیں سن سکتے؟ وہ یہی سوالات پاٹھ شالا کے گروجی سے بھی کرتا ہے جو بچوں کو روز دِویہ بانی سناتے ہیں۔ گروجی پہلے تو ان سوالوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بالیشور کے کافی اصرار پر وہ یوں گویا ہوتے ہیں : ’’بات یہ ہے کہ برہما نے ہمیں ارتھات ہمارے پرتھمہ پور وَج کو اپنے سر سے جنم دیا تھا اور جھگرو کے پرتھم پور وَج کو اپنے پاؤں سے نکالا تھا۔ سر اور پاؤں میں جو انتر ہے وہی ہم میں اور جھگرو میں ہے۔ ہم سر کا استھان رکھتے ہیں اور جھگرو پاؤں کا۔ سر اوپر ہوتا ہے اور پاؤں نیچے‘‘ (ص ۳۳)۔ گروجی بقیہ سوالوں کے جواب دینے سے گریز کرتا ہیں اور اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ بالیشور کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، لیکن وہ ان سب باتوں سے بے حد فکر مند رہتا ہے۔ بالیشور ایک رات خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک نہایت خوف ناک سانپ بابا کے کمرے میں سے نکل کر باہر جاتا ہے اور کبوتروں اور میمنوں کو ڈس کر پھر بابا کے کمرے میں آ جاتا ہے۔ خوف اور دہشت سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بہت دیر تک اس خواب سے پریشان رہتا ہے۔ ماں اسے تھپکی دے کر دوبارہ سلادیتی ہے۔
بالیشور کے گھر میں چمٹولی میں رہنے والے بھیکو کی نوعمر بیٹی بندیا داسی (ملازمہ) ہے۔ وہ اس کی ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ ایک دن وہ بابا کے کمرے سے نہایت بدحواسی کے عالم میں روتی ہوئی اور منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تیزی سے باہر نکلتی ہے۔ اس کی ساڑی پر خون کے دھبے نمایاں ہیں۔ بالیشور یہ منظر دیکھتا ہے، لیکن اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بابا کو جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ بالیشور نے بندیا کو اس حالت میں ان کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ بندیا کا کوئی گھاؤ تھا جو پھوٹ گیا ہے اور اس سے خون بہنے لگا ہے۔ اسے فوراً کسی وید کے پاس جانا چاہیے۔ بالیشور کی ماں کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ حیران و ششدر رہ جاتی ہے۔ ماں کی اتنی زیادہ حیرانی کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ماں بالیشور سے کہتی کہ بابا کے وشرام کے سمے ان کے کمرے کی طرف مت جایا کرو۔ ان کے وشرام میں بادھا پڑتی ہے۔ بالیشور اس واقعے سے اُس وقت کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ لیکن اس کی تصویر اُس کے پردۂ ذہن پر نقش ہو کر رہ جاتی ہے۔
بالو اور بالیشور کی دوستی، ان دونوں کے درمیان سماجی تا برابر یوں کے باوجود، پروان چڑھتی ہے۔ وہ دونوں ندی کے کنارے بیٹھے گھنٹوں باتیں کیا کرتے ہیں۔ بالیشور بالو کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ دِویہ بانی سن لے۔ بالو صاف منع کر دیتا ہے۔ اس تصور سے اس کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ اگر اس نے دِویہ بانی سن لی تو اس کا بھی حشر وہی ہو گا جو اس کے باپ جھگرو یا چمٹولی کے دوسرے دلتوں کا ہوا تھا۔ جب بالیشور بالو کو اس بات کا پورا یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرے گا تب بڑی مشکل سے وہ دِویہ بانی سننے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ دِوّیہ بانی اسے اچھی تو لگتی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خوف بھی سما جاتا ہے کہ اگرکسی کو اس بات کا پتا چل گیا تو کیا ہو گا۔ دھیرے دھیرے بالو میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں بابا کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن انھیں اپنے مخبروں کے ذریعے یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ بالو نے دِویہ بانی سن لی ہے، لیکن یہ بات ان کے لیے معما بنی رہتی ہے کہ بالو کو دویہ بانی کس نے سنائی۔ ان کا شک بالیشور پر جاتا ہے، لیکن ان کے پوچھنے پر وہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ بالو کو ودیہ بانی اس نے نہیں سنائی۔ بابا اس بات سے بے حد فکر مند رہتے ہیں۔ بالآخر وہ بالو ہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے ودیہ بانی سنی ہے، اور اگر سنی ہے تو یہ اسے کس نے سنائی۔ بابا اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا نرک (دوزخ) میں جاتا ہے، اسے کوڑھ ہو جاتا ہے اور وہ منہ سے لہو تھوکنے لگتا ہے۔ بابا جب اسے اس بات کا پورا یقین دلاتے ہیں کہ سچ بولنے پر اس کی سزا میں تخفیف کر دی جائے گی اور معمولی سی سزادے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا اور دِویہ بانی سنانے والے کو بھی معاف کر دیا جائے گا، بت بابا کی باتا کا یقین کرتے ہوئے بالو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس نے دویہ بانی سنی ہے اور سنانے والا بالیشور ہے۔ بابا اس بات سے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ دویہ بانی بالو کو بالیشور نے سنائی ہے۔ اب بابا کو اپنے پوتے کو بچانے کی فکر ستانے لگی ہے، کیوں کہ انصاف کی رو سے بالیشور کو بھی ڈنڈ (سزا) ملنا چاہیے، کیوں کہ دِویہ بانی بالو کو اسی نے سنائی ہے۔ اب بابا بالو سے یہ جھوٹ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اس نے دِویہ بانی بالیشور سے نہیں سنی، بلکہ خود چپکے سے کان لگا کر سن لی۔ بالو بابا سے کہتا ہے کہ کیا ایسا کہنا جھوٹ بولنا نہیں ہو گا۔
اس واقعے کے چند روز بعد گاؤں میں ہون کنڈ تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے آس پاس لوگ جمع ہونے لگتے ہیں اور بالو کو ڈنڈ دیے جانے کی پوری تیاری کر لی جاتی ہے۔ بابا ماتھے پر تلک لگائے پوری تیاری کے ساتھ ہَون کنڈ کے چبوترے پر براجمان ہوتے ہیں۔ بالیشور بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور سچ سچ بتا دیتا ہے کہ بالو کو دِویہ بانی اسی نے سنائی ہے، اس لیے سزا کا وہ بھی مستحق ہے۔ بابا اس کی کوئی بات نہیں سنتے ہیں اور مجمع سے کہتے ہیں کہ بالو ان کا مِتر (دوست) ہے، اس لیے وہ اسے ڈنڈ (سزا) سے بچانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ وہ اس وقت اپنے کر لیتے ہیں۔ بالو کو جس کے ہاتھ پیر مضبوط رسی سے بندھے ہوتے ہیں جانور کی طرح پچھاڑ کر زمین پر گرا دیا جاتا ہے۔ بابا پتیلے میں کھولتے ہوئے مادے (سیسے) کو بالو کے کان میں ڈال دیتے ہیں۔ بالو بلبلا اٹھتا ہے، اس کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں۔ اس کی چیخ سے زمین و آسمان دہل اٹھتے ہیں۔ چمٹولی کے بچے اپنے کانون میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن بابا کے چہرے پر اس کا کوئی اثر نمودار نہیں ہوتا ہے۔ بالیشور اس اندوہ ناک منظر کو تاب نہ لا کر سکتے کے عالم میں چلا جاتا ہے، پھر اچانک چلا اٹھتا ہے، ’’آپ بڑے نردئی (بے رحم)ہیں بابا! ایک دم کٹھور جیسے پتھر ہوتا ہے۔ ۔ ۔ پتھر تو پگھل بھی جاتا ہے، آپ پتھر سے بھی ادھک (زیادہ) کٹھور ہیں ‘‘ (ص ۱۱۲) بالیشور بابا کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ’’اس دن میرے سپنے میں جو سانپ آپ کے کمرے سے نکلا تھا، وہ سانپ نہیں تھا، بلکہ آپ سویم (خود ) تھے۔ آپ ہی نے اس دن کبوتروں کو ڈسا تھا، میمنوں کو کاٹا تھا، آپ سچ مچ۔ ۔ ۔ ۔ ‘‘ (ص ۱۱۲)۔
اس خوں چکاں واقع کے بعد سے بالیشور اداس اور مغموم رہنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی وہ رونے بھی لگتا ہے۔ اس کی ماں سے اس کی یہ گم سم حالت دیکھی نہیں جاتی ہے۔ وقت گذرتا جاتا ہے۔
بالیشور جوان ہو جاتا ہے اور سنجیدہ بھی۔ وہ گھنٹوں ندی کے کنارے بیٹھ کر کچھ سوچتا رہتا ہے، لیکن تنہا اور اداس۔ ایک دن ندی سے لوٹتے ہوئے وہ نالے کے گندے پانی میں چمٹولی کے بہت سے مردوں عورتوں اور لڑکے لڑکیوں کو ایک ساتھ نہاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کے پاؤں ٹھٹک جاتے ہیں۔ مرد تو سر سے پاؤں تک برہنہ ہو کر نہا رہے تھے۔ عورتوں کے جسم کا اوپری نصف حصہ عریاں تھا۔ صرف ناف سے نیچے جانگھ تک ساڑی لپٹی ہوئی تھی۔ پانی میں ڈبکی لگاتے وقت جب ساڑی اوپر اٹھتی تھی تو ان کا ٹانگیں اور رانیں ننگی ہو جاتی تھیں۔ بالیشور ان عورتوں کو گندے پانی میں نہاتے اور ڈبکی لگاتے ہوئے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے اور اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتا ہے۔ چمٹولی کے مردوں اور عورتوں کا نالے کے گندے پانی میں نہانا ان کا روز کا معمول تھا۔ نہ مرد عورتوں کو نیم برہنہ دیکھ کر جنسی جذبات سے مغلوب ہوتے تھے اور نہ عورتوں پر مردوں کی برہنگی کا کوئی اثر نمایاں ہوتا تھا، لیکن یہ مناظر پوری قوت کے ساتھ بالیشور کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ اب نالے پر جانا اور ان مناظر سے لطف اندوز ہونا اس کا روز کا معمول بن جاتا ہے۔ ایک دن نالے میں نہاتی ہوئی ایک لڑکی جو اس کی ہم عمر تھی اور جس کا جسم گداز اور چھاتیاں تنی ہوئی تھیں اس کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ بالیشور اب جب بھی نالے پر جاتا تو نہاتی اور ڈبکی لگاتی ہوئی عورتوں اور لڑکیوں میں اسے ضرور تلاش کرتا۔ ایک دن جب وہ لڑکی نہا کر نالے سے باہر نکلتی ہے تو بالیشور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ لڑکی سے اس کا نام پوچھتا ہے۔ لڑکی پیچھے مڑ کر کہتی ہے، ’’بندیا‘‘۔ یہ نام بالیشور کو کچھ مانوس سا لگتا ہے۔ پھر وہ لڑکی سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ پہلے میں آپ کے گھر میں کام کرتی تھی۔ بالیشور کہتا ہے کہ اچھا تو تم وہ بندیا ہو، پھر کام کرنا کیوں چھوڑ دیا۔ وہ کہتی ہے، ’’بالا نے مجھے نکال دیا تھا‘‘۔ ’’کیوں ‘‘؟ بالیشور کے اس سوال پر بندیا بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ بالیشور اب بندیا سے تقریباً روز ملنے لگتا ہے۔ وہ تخیل میں بندیا کو گندے پانی کے نالے سے نکال کر ندی میں لے جاتا ہے جہاں وہ صاف و شفاف پانی میں نہا کر اجلی اور پرکشش ہو کر نکلتی ہے۔ وہ بندیا کو اپنے سے لگا لیتا ہے۔ بندیا کو اب احساس ہوتا ہے کہ نالے کا پانی کتنا گندا اور بدبو دار ہے۔ وہ کنویں سے پانی لا کر اب اپنے گھر میں نہاتی ہے۔ بالیشور بندیا کے دام محبت میں بری طرح گرفتار ہو جاتا ہے اور اپنی سدھ بدھ کھوبیٹھتا ہے۔ بندیا کی بے قراری بھی روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ ایک رات بندیا اور بالیشور جب جھاڑی کے پیچھے ملے تو ’’بے قابو ہو کر بالیشور نے بندیا کو اپنی آغوش میں بھرلیا۔ بانہوں کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ ۔ ۔ وہ بندیا میں اور بندیا اس میں بے روک ٹوک اترتے چلے گئے۔ ‘‘ (ص ۱۳۳)۔
بندیا بالیشور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بالیشور اپنی ماں کے سامنے بندیا سے شادی کی تجویز رکھتا ہے۔ ماں اس تجویز کو سختی سے ناپسند کرتی ہے اور بالیشور کو اپنے اس ارادے سے باز رہنے کو کہتی ہے، کیوں کہ ایک شودر لڑکی برہمن خاندان کی بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ بالیشور ماں سے کہتا ہے کہ وہ بندیا سے پیار کتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ برہمن کا بچہ ہے، کسی شودر کا بچہ نہیں۔ وہ اسے پالے پوسے گا، اس کی پرورش کرے گا، اور اسے پاٹھ شالا بھیجے گا جہاں ہ دوسرے بچوں کی طرح دِویہ بانی سنے گا۔ ماں کہتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوسکتا۔ ماں صرف یہی نہیں سوچتی ہے کہ بندیا ایک شودر ہے، بلکہ اس کا ذہن اُس طرف بھی جاتا ہے کہ بندیا کے ساتھ بابا کا جنسی تعلق رہ چکا ہے۔ ماں یہ راز بالیشور سے چھپاتی ہے، لیکن جب بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے تو ماں کو یہ راز افشا کرنا ہی پڑتا ہے۔ بالیشور کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھر کر آ جاتا ہے جب ایک دن بندیا بدحواسی کے عالم میں روتی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھے تیزی سے بابا کے کمرے سے نکلتی تھی اور اس کی ساڑی خون کے دھبوں سے داغ دار تھی۔ بالیشور پر اب یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ بندیا کی ساڑی میں لگا وہ خون گھاؤ پھوٹنے کا خون نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ دوسری تھی۔ بابا کی اس ذلیل حرکت علم سے بالیشور پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں بابا کے خلاف شدید نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ماں سے کہتا ہے کہ بابا نے بہت بڑا پاپ کیا ہے۔ ماں بابا کے اس کالے کر توت کا دفاع کرتی ہے اور کہتی ہے، ’’پاپ کیسا؟ باب نے کوئی پاپ نہیں کیا ہے۔ داسی کے ساتھ سمبندھ (تعلق) رکھنا واستو میں کوئی پاپ نہیں۔ داسی ہوتی ہی اس لیے ہے کہ سوامی جس پر کار چاہے اس کا اپیوگ (استعمال) کرے۔ تم نے بھی داسی کا رپیوگ کیاہے، اس لیے یہ کسی وِوھی وِدھان (قانون) کے وِردھ (خلاف) نہیں ‘‘ (ص ۱۴۰)۔ ماں بالیشور سے صاف لفظوں میں کہہ دیتی ہے کہ بندیا کے گربھ وتی (حاملہ) ہو جانے کا ارتھ (مطلب ) یہ نہیں کہ وہ اسے اپنی پتنی (بیوی) بنالے۔ ایسا کبھی نہیں ہوسکتا۔ بالیشور اپنی ماں کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ بندیا سے اس کا جنسی تعلق شہوانی جذبے سے مغلوب ہو کر نہیں ہوا ہے، بلکہ اس تعلق کی بنیاد دونوں کے درمیان سچی محبت ہے۔
بابا کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بالیشور بندیا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ آگ بگولا ہو اٹھتے ہیں اور بندیا کو راستے سے ہٹانے کی تدبیریں سوچنے لگتے ہیں۔
ایک دن چمٹولی میں زبردست کہرام مچتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندیا کو سانپ ڈس لیتا ہے۔ بالیشور کو جب پتا چلتا ہے تو وہ بدحواسی کے عالم چمٹولی کی طرف بھاگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھیکو کے دروازے کے سامنے بندیا کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہی بندیا جو اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ بالیشور صدمے سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ وہ صرف بندیا ہی کی لاش نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اسے اپنے بچے کی لاش بھی نظر آتی ہے جو عام نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ غم و غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ تہہ و بالا کر کے رکھ دے گا۔ اچانک دِویہ بانی کے بول اس کے کانوں میں گونجنے لگتے ہیں جس سے اس کا اضطراب کم ہو جاتا ہے اور من کو شانتی ملتی ہے۔
ایک دن بامھن ٹولے میں عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے۔ لوگ جوق در جوق ہَون استھل کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بالیشور بھی حیرت و استعجاب کے عالم میں بھیڑ کو چیرتا اور کودتا پھاندتا ہون استھل کی طرف بڑھتا ہے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہے کہ ہَون کنڈ کے چبوترے کے اوپر ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی سرخ زبان بار بار منہ سے باہر نکل رہی ہے۔ اس کا پھن بھی چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ یہ وہی سانپ ہے جس نے کچھ دیر پہلے کسی کے گھر میں گھس کر میمنون کو ڈسا تھا۔ مجمع پر خوف و ہراس طاری ہے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ آگے بڑھے۔ بالیشور کچھ دیر تک اس سانپ کی طرف اپنی نظریں گڑا کر دیکھتا ہے، پھر تیزی سے اس کی طرف لپک کر اور آن کی آن میں اس کی گردن کو منہ کے پاس سے پکڑ کر چبوترے سے اٹھا لیتا ہے۔ سانپ اپنی پوری طاقت سے بالیشور کی مٹھی سے نکل جانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالیشور کی گرفت مضبوط ہوتی جاتی ہے اور سانپ کی گردن کستی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا منہ نکل آتا، زبان اینٹھ جاتی ہے، آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، دُم بے حس و حرکت ہو کر لٹک جاتی ہے اور اس کا پورا وجود ساکت ہو جاتا ہے۔
بالیشور اطمینان کا سانس لیتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ رات کی دیوار ڈھا دی گئی ہے اور روشنی تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ وہ خیالوں میں کھو جاتا ہے۔ اب چمٹولی کے لو گ نالے میں نہانے کے بجائے ندی میں نہائیں گے۔ ان کے بچے بھی اب پاٹھ شالا جائیں گے اور وہ بھی سب کے ساتھ مل کر دویہ بانی سنیں گے۔
(۴)
’دِویہ بانی ‘ کا پلاٹ کوئی لمبا چوڑا یا پیچیدہ پلاٹ نہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی انوکھا پن ہے، لیکن اس کے سماجی و تہذیبی تناظر نے اسے دل چسپ بنا دیا ہے۔ مذہب کی آڑ میں سماج کے کم زور طبقے پر طبقۂ اشرافیہ کے ظلم و جبر، استحصال اور سماجی نا برابری کے خلاف احتجاج اور کچھ کرنے گذرنے کا عزم اس بیانیہ کے پلاٹ کو بیحد جان دار اور متحرک (Dynamic) بنا دیتا ہے۔ دِویہ بانی کی زبان اس کے پلاٹ کے عین مطابق ہے، لیکن سنسکرت کے تتسم الفاظ کا اکثر بے دریغ استعمال اردو قارئین کی سماعت پر گراں گذرتا ہے۔
اس ناول کے بنیادی کردار تین ہیں : بابا، بالیشور اور بندیا۔ بابا طبقۂ اشرافیہ کے نمائندہ ہیں، لیکن ان کی شخصیت تضادات سے بھر پور ہے۔ وہ اس ناول میں منفی کردار نبھاتے ہیں۔ بہ ظاہر وہ مذہب کے ٹھیکے دار بنتے ہیں، لیکن ان کے کردار کی خباثت انھیں بدی کی علامت (Symbol) بنا دیتی ہے۔ بالآخر بدی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بالیشور (بابا کا پوتا) ایک حوصلہ مند اور پُر عزم نوجوان ہے جو سماجی کے اونچ نیچ اور ذات پات کی تفریق کے خلاف احتجاج کرتا ہے اور سماجی و تہذیبی نا برابری کو جڑسے اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرح بزدل نہیں، جو باب سے لڑنے اور احتجاج کرنے کے بجائے اپنا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور اس کی بیوی (بالیشور کی ماں ) تمام عمر اس کی راہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ بندیا بابا کی جنسی ہوس کا شکار ایک مجبور وبے سہارا دلت لڑکی ہے۔ جب وہ بالیشور کی توجہ کا مرکز بنتی ہے تو اس پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، لیکن قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ وہ بالیشور کے بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی تو ہے، لیکن اس کی بیوی بننے اور اس کے بچے کی ماں بننے سے پہلے ہی وہ ناگہانی موت کا شکار ہو جاتی ہے۔ بالیشور کی ماں اور بالو (بالیشور کا بچپن کا دوست) بھی اس ناول کے اہم کردار ہیں، لیکن انھیں مرکزی حیثیت حاصل نہیں۔
غضنفر نے ’دِویہ بانی‘ میں استعاراتی اسلوب سے بھرپور کام لیا ہے۔ سانپ کے استعارے (Metaphor) کو انھوں نے بڑی فنی مہارت کے ساتھ برتا ہے۔ یہ اس بیانیہ میں بدی، ظلم و جبر اور طبقہ اشرافیہ کی قوت کے استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ سانپ کا خاتمہ حقیقتاً بابا کے ظلم و جبر اور قوت و اقتدار (Authorities) کا خاتمہ ہے۔ بلکہ خود بابا کا خاتمہ ہے۔ ’دِویہ بانی‘ میں اشارتی اسلوب سے بھی کام لیا گیا ہے۔ اس میں ہندو دیو، لائی عناصر کی جھلک بھی صاف دکھائی دیتی ہے۔ اس ناول میں غضنفر نے فلیش بیک (Flash back) سے بھی کئی جگہ کام لیا ہے جسے انھوں نے ’جنتن ‘ کا نام دیا ہے۔ فلیش بیک میں ماضی و مستقبل کی تصویریں بنتی بگڑتی چلی جاتی ہیں اور زمان و مکاں کی قیود سے آزاد ہوتی ہیں۔ یہ بیانیہ کا ایک اہم عنصر قرار دیا گیاہے۔ غضنفر کو جزئیات نگاری پر بھی کمال حاصل ہے۔ وہ جس صورتِ حال کو بھی بیان کرتے ہیں اس کی تمام تفصیلات پیش کر دیتے ہیں۔ منظر نگاری بھی وہ بہت اچھی کر سکتے ہیں۔ باغ کا منظر یا نہانے کا منظر بیحد دل کش ہے۔
’دِویہ بانی‘ ایک ایسا دلت بیانہ (Dalit Narrative) ہے جو اردو کے دلت لٹریچر میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے اولیت کا مرتبہ بھی حاصل ہے کہ اس سے قبل اردو میں دلت لٹریچر کی روایت بہت کم زور تھی۔ فنی سطح پر بھی غضنفر کا یہ ایک کامیاب تجربہ ہے جو ہر لحاظ سے لائقِ دادو تحسین ہے۔
تشکر: مصنف جنہوں نے اس کی فائل فراہم کی
ان پیج سے تبدیلی، تدوین اور ای بک کی تشکیل: اعجاز عبید




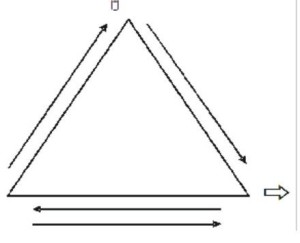

مجھے یہ کتاب ضرورت ہے ، اگر آپ مجھے PDF format میں مہیا کر دیں تو بہت مہربانی ہو گی۔ جزاک اللہ